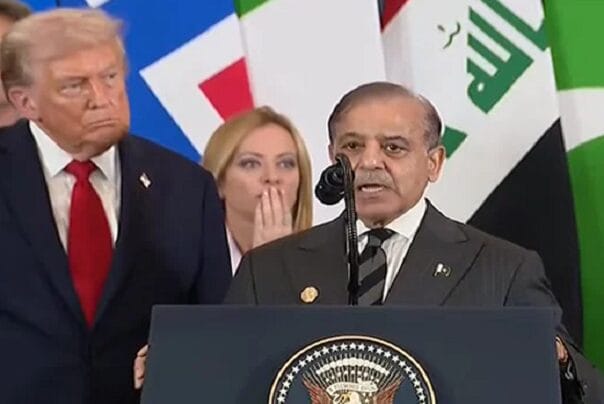پاکستان میں انسانی حقوق اور شہری آزادیوں پر پابندی اکثر بلا قانونی جواز کے لگا دی جاتی ہے، جو ریاستی اداروں کی ثقافت میں گہری جڑیں رکھتی ہے۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ حکمران اشرافیہ اور اختیارات کے غلط استعمال کرنے والی بیوروکریسی نوآبادیاتی دور کے ظالمانہ قوانین کو ختم یا ترمیم کرنے سے گریزاں ہے، جو برطانوی راج سے وراثت میں ملے ہیں۔ یہ قوانین، جو پہلے برطانوی ہند کے تعزیری قانون کا حصہ تھے اور اب پاکستان کے تعزیری قانون میں شامل ہیں، نہ صرف برقرار رہے بلکہ نئے شقوں کے ساتھ ان میں اضافہ بھی کیا گیا ہے، جس سے یہ مزید جابرانہ بن گئے ہیں۔ایک واضح مثال برطانوی ہند کے تعزیری قانون 1867 کا دفعہ 124-اے ہے، جو مقامی انتظامیہ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ کسی بھی جائز، پُرامن سیاسی، مذہبی، یا ثقافتی احتجاج کو غیر قانونی قرار دے دیں۔ اس کے علاوہ، یہ حکام کو مظاہرین پر غداری اور بغاوت کے الزامات لگانے کی اجازت بھی دیتا ہے۔ یہ دفعہ برطانوی سلطنت نے ہندوستانی برصغیر میں اختلاف رائے کو دبانے کے لئے بڑے پیمانے پر استعمال کی، جس کے نتیجے میں ہزاروں کیسز سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف دائر کیے گئے۔پاکستان کے قیام کے بعد یہ نوآبادیاتی دفعہ عبوری ایکٹ 1935، آئین 1956، صدارتی آئین 1964، اور آئین 1973ء میں بھی نافذ العمل رہی۔ ملک کی تاریخ میں ہر جمہوری حقوق اور آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والی تحریک کو اس دفعہ کے بے دریغ استعمال کا سامنا کرنا پڑا۔ حالانکہ لاہور ہائی کورٹ نے اس دفعہ کو غیر قانونی قرار دیا تھا کیونکہ یہ پاکستان کے آئین کے بنیادی حقوق سے متصادم ہے، لیکن اقتدار میں آنے والی کسی بھی سیاسی جماعت نے کبھی اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا، جس سے نوآبادیاتی جبر کی روایت برقرار رہی۔حالیہ دنوں میں وفاقی حکومت نے شہری آزادیوں پر مزید قدغنیں لگانے کی کوشش کی۔ ستمبر کے پہلے ہفتے میں، حکومت نے ایک خصوصی ایکٹ متعارف کروایا جس نے آئین کی کئی شقوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسلام آباد میں پُرامن اور قانونی اجتماع کے حق پر سخت پابندیاں عائد کر دیں۔ نئے قانون کے تحت ایسے اجتماعات کو مقامی مجسٹریٹ کی پیشگی اجازت سے مشروط کر دیا گیا اور خلاف ورزی پر تین سال تک کی قید اور غیر معینہ جرمانے جیسی سخت سزائیں عائد کی گئیں۔ یہ اقدام نوآبادیاتی کنٹرول کی باقیات کی عکاسی کرتا ہے، جہاں ریاست کی گرفت شہری آزادیوں پر سخت ہوتی جا رہی ہے، جو پاکستان کو جمہوری اصولوں کی جانب بڑھنے کی بجائے پیچھے دھکیل رہی ہے۔بلوچستان میں صورت حال مزید سنگین ہے۔ یہاں پاکستان کے تعزیری قانون کے دفعہ ۱۲۴-اے کو فعال طور پر نافذ کیا جا رہا ہے، اور وفاقی حکومت نے سیکیورٹی فورسز، انٹیلیجنس ایجنسیز، اور پولیس کو خصوصی اختیارات دیے ہیں، جن میں دہشت گردی کے شبے میں بغیر وارنٹ چھاپے مارنا اور ملزمان کو تین ماہ تک حراست میں رکھنا شامل ہے۔ یہ اقدامات غیر انسانی اور غیر جمہوری عمل کی نمایاں مثال ہیں، جو سیکیورٹی فورسز کو بے لگام اختیارات دے کر شہریوں کے بنیادی حقوق کو مزید مجروح کرتے ہیں۔نوآبادیاتی دور کے ان قوانین اور نئی پابندیوں کا پاکستان کی جمہوریت پر گہرا اور نقصان دہ اثر پڑ رہا ہے۔ یہ قوانین جو اختلاف رائے کو دبانے اور نوآبادیاتی کنٹرول کو برقرار رکھنے کے لیے بنائے گئے تھے، جمہوری اصولوں جیسے اظہار رائے کی آزادی، اجتماع کی آزادی اور احتجاج کے حق کے بالکل برعکس ہیں۔ ان کا تسلسل نہ صرف انفرادی آزادیوں کو مجروح کرتا ہے بلکہ قوم کے مجموعی جمہوری ڈھانچے کو بھی کمزور کرتا ہے۔یہ قوانین خوف اور دہشت کا ماحول پیدا کرتے ہیں، جہاں شہری اختلافی خیالات کا اظہار کرنے یا سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے گھبراتے ہیں۔ بغاوت یا دیگر سنگین الزامات کا سامنا کرنے کے خوف سے پُرامن احتجاج یا حکومت پر تنقید کے حق کو استعمال کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، جو جمہوریت کی بنیادی اقدار کے منافی ہے، جو کھلی گفتگو اور خیالات کے آزادانہ تبادلے پر منحصر ہوتی ہے۔اس کے علاوہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی ایجنسیز کو دیے گئے بے لگام اختیارات قانون کی حکمرانی کو مجروح کرتے ہیں اور ایک ایسا کلچر فروغ دیتے ہیں جہاں ریاستی احتساب کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ جمہوریت کے لئے مضر ہے، جہاں حکومت کو عوام کی خدمت کرنی چاہیے نہ کہ ان کو دبا کر رکھنا چاہیے۔ ان قوانین کا انتخابی استعمال اکثر سیاسی مخالفین، کارکنوں، اور محروم طبقات کو نشانہ بناتا ہے، جس سے حکمران اشرافیہ کی گرفت مضبوط ہوتی ہے اور حقیقی سیاسی مقابلے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔جمہوری اداروں پر بھی اس کے شدید اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جب عدلیہ کے فیصلے ایسے جابرانہ قوانین کے خلاف نظر انداز کیے جاتے ہیں یا ان پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا تو یہ اختیارات کی علیحدگی کی توہین کرتا ہے اور عدلیہ کی آزادی کو کمزور کرتا ہے، جو صحت مند جمہوریت کے لئے ضروری ہے۔ سیاسی جماعتوں کی طرف سے عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرنا آئینی حقوق اور اصولوں کو برقرار رکھنے میں وسیع تر ادارہ جاتی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔پاکستان کو واقعی اپنے آئین کے اصولوں کا احترام کرنے کے لیے اپنے شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لئے پرعزم ہونا پڑے گا اور یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ریاست کے تمام اقدامات قانون کے دائرے میں اور انسانی وقار کے احترام پر مبنی ہوں۔ نوآبادیاتی دور کے ان قوانین کی موجودگی اور حالیہ حکومتی اقدامات ملک میں قانونی اور ادارہ جاتی اصلاحات کی فوری ضرورت کو اجاگر کرتے ہیں۔ ایک زیادہ منصفانہ اور جمہوری معاشرے کی جانب پیش رفت کے لئے ضروری ہے کہ پرانے، جابرانہ قوانین کو ختم کیا جائے اور ایسی پالیسیاں نافذ کی جائیں جو شہری آزادیوں کو وسعت دیں۔پاکستان کا مستقبل نوآبادیاتی قوانین کے خاتمے اور نئی پابندیاں متعارف کروانے کی مخالفت پر منحصر ہے۔ آزادی، وقار اور قانون کی حکمرانی کے لئے جدوجہد محض تاریخی نہیں بلکہ یہ ایک مسلسل کوشش ہے جس کے لئے مستعدی، عزم، اور جمہوریت اور انسانی حقوق کی حقیقی پاسداری کی ضرورت ہے۔ تمام کے لئے حقیقی آزادی اور انصاف کے سفر میں یہ جدوجہد جاری ہے، لیکن یہ پاکستان کے مستقبل کے لئے ضروری ہے۔ ایک زیادہ جمہوری پاکستان کے لئے جنگ صرف پرانے قوانین کے خاتمے کی نہیں بلکہ اس بات کو یقینی بنانے کی ہے کہ ریاست اپنے لوگوں کا ان کے حقوق اور آزادیوں کے احترام کے ساتھ کے بہترین سلوک کرے۔
محصولات میں کمی
جیسا کہ توقع تھی، وفاقی ریونیو بورڈ ملکی معیشت کی سست روی کے باعث اپنے طے شدہ محصولات کے اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہو رہا ہے۔ موجودہ ٹیکس دائرے میں شرح میں اضافے نے معیشت کے رسمی شعبے میں نمو کی رفتار کو مزید سست کر دیا ہے۔درآمدات میں کمی اور پاکستانی روپے کی مستحکم شرح مبادلہ کے نتیجے میں درآمدات سے حاصل ہونے والے محصولات میں کمی واقع ہوئی ہے، جس پر وفاقی ریونیو بورڈ اپنی نصف سے زیادہ وصولیوں کے لئے انحصار کرتا ہے۔آگے چل کر، شرح سود میں کمی کا محصولات پر منفی اثر پڑے گا، کیونکہ تقریباً 40 فیصد سود کی آمدنی پر ٹیکس عائد ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں ضمنی بجٹ کا امکان بڑھ رہا ہے۔اطلاعات کے مطابق، وفاقی ریونیو بورڈ نے یکم اکتوبر سے تمام ودہولڈنگ ٹیکس کی شرح میں ایک فیصد اضافے کی تجویز پیش کی ہے۔ اگر یہ قدم اٹھایا گیا تو یہ ٹیکس دائرہ کار کو وسیع کرنے اور مؤثر براہ راست ٹیکس بڑھانے کی کوششوں کے بالکل برعکس ہوگا۔ودہولڈنگ ٹیکس کی شرح میں اضافہ کرنے سے ایک اور مسئلہ یہ ہو گا کہ سال کے اختتام پر کم ٹیکس وصول ہوگا، کیونکہ ودہولڈنگ ٹیکس کی وصولی اکثر کل ٹیکس واجبات سے تجاوز کر جاتی ہے۔ یہ عملی طور پر مسائل کو مزید آگے بڑھانے کے مترادف ہے۔وفاقی ریونیو بورڈ کی توجہ قلیل مدتی وصولیوں پر مرکوز ہے تاکہ ماہانہ اور سہ ماہی اہداف پورے کئے جا سکیں اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے اہداف کے مطابق رہ سکیں، حالانکہ ابھی تک پروگرام کی منظوری بورڈ نے نہیں دی ہے۔مسئلہ یہ ہے کہ معیشت کے تقریباً نصف شعبوں پر ٹیکس نہیں لگایا جا رہا۔ اور بااثر حلقوں، چاہے وہ تاجر ہوں یا بڑے زمیندار، کی جانب سے غیر ٹیکس شدہ شعبوں پر ٹیکس عائد کرنے کی شدید مزاحمت ہو رہی ہے جبکہ پہلے سے ٹیکس شدہ شعبوں سے وصولی اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے۔زیادہ ٹیکس کی شرح اور تاجروں اور ریٹیلرز پر ٹیکس کی عائدگی نے معیشت کو مزید سست کر دیا ہے، جیسا کہ مختلف صنعتوں میں حجم میں کمی دکھائی دے رہی ہے۔ دودھ اور دیگر مصنوعات پر ٹیکس کی شرح میں اضافہ ہوا ہے اور ان شعبوں کے رسمی حصے میں نمایاں کمی نظر آ رہی ہے۔تنخواہوں پر زیادہ ٹیکس کی شرح نے دستیاب آمدنی کو کم کر دیا ہے اور صارفین کو اپنے غیر ضروری اخراجات میں کمی کرنی پڑی ہے۔ ٹیکس اصلاحات کا مقصد براہ راست محصولات میں بہتری لانا ہے، اور یہ مرحلہ وار ودہولڈنگ ٹیکس کی شرح کو کم کر کے حاصل کیا جانا چاہیے۔ لیکن بظاہر، وفاقی ریونیو بورڈ اس کے برعکس منصوبہ بندی پر مجبور محسوس کر رہا ہے۔بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ معاہدہ ہے کہ یکم جنوری 2025 سے زرعی ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ اس میں بھی چیلنجز ہیں۔ بہت سے واقعات میں زمین کی ملکیت کی منتقلی وارثین کو نہیں کی گئی، جو خواتین کو ان کے قانونی حقوق دینے سے گریز کرتے ہیں اور زمین کی ملکیت مردہ آباؤ اجداد کے نام پر ہی رہتی ہے۔وفاقی ریونیو بورڈ مردہ افراد سے ٹیکس کیسے وصول کرے گا؟ ریٹیلرز کے معاملے میں، حکومت معیشت کو دستاویزی شکل دینے میں ناکام ہو رہی ہے کیونکہ مبینہ طور پر ریٹیلرز کے مطالبے کے سامنے جھک گئی ہے کہ وہ اثاثوں اور بینک اکاؤنٹس کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کریں گے، سوائے اس ایک اکاؤنٹ کے جہاں ریفنڈ، اگر کوئی ہو، کریڈٹ کیا جانا ہے۔ٹیکسٹائل کے شعبے کے کھلاڑی کہتے ہیں کہ وفاقی ریونیو بورڈ جان بوجھ کر ریفنڈز میں تاخیر کر رہا ہے تاکہ قلیل مدتی میں بہتر وصولیوں کی نمائش کی جا سکے۔ برآمد کنندگان اپنی آمدنی پر 2-2.5 فیصد ٹیکس ادا کر رہے ہیں جس میں سے کچھ رقم قابل واپسی ہے اگر انکم ٹیکس وصولی سے کم ہو۔لیکن وفاقی ریونیو بورڈ اس میں تاخیر کر رہا ہے، جو بلند حقیقی مثبت شرح سود کے دنوں میں برآمد کنندگان کی ورکنگ کیپٹل لاگت میں اضافہ کر رہا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سال کے آخر میں ریفنڈز کے زیادہ دعوے ہوں گے اور آخری ماہ میں بہت کم محصولات جمع ہوں گے۔وفاقی ریونیو بورڈ سال کے مکمل اہداف کے مقابلے میں پیچھے رہ جائے گا۔ تاہم، قلیل مدتی مسائل اس وقت سیاسی صورتحال کی نازکی اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ طے شدہ اہداف کے دباؤ کی وجہ سے مرکز نگاہ ہیں۔خلاصہ یہ ہے کہ صورتحال غیر مستحکم ہے، اور وفاقی ریونیو بورڈ کو دوبارہ غور کرنے اور براہ راست ٹیکس وصولی کو بڑھانے کے لئے حکمت عملی کو دوبارہ ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ بصورت دیگر، اگلا سال موجودہ دائرہ کار کے لئے مزید بُرا ہو سکتا ہے۔
پلاسٹک آلودگی کا بحران
پلاسٹک کی آلودگی ہمارے دور کے سب سے سنگین ماحولیاتی چیلنجز میں سے ایک بن کر ابھری ہے، اور جنوبی ایشیا پر اس کے اثرات خاص طور پر شدید ہیں۔ عالمی بینک کی حالیہ رپورٹ “پلاسٹک کی لہریں: جنوبی ایشیا میں سمندری پلاسٹک کی آلودگی کی جھلک” اس بحران کی وسعت پر روشنی ڈالتی ہے۔ یہ رپورٹ ناقص کچرا انتظامیہ کے تباہ کن نتائج اور پلاسٹک آلودگی کے بڑھتے ہوئے خطرے سے نمٹنے کے لیے مربوط علاقائی کارروائی کی فوری ضرورت کو اجاگر کرتی ہے۔ جنوبی ایشیا تقریباً ایک چوتھائی عالمی آبادی کا گھر ہے اور اسے گنجان آباد شہری مراکز اور وسیع دیہی علاقوں کی خصوصیت حاصل ہے۔ تیزی سے صنعتی ترقی اور شہری کاری کے ساتھ مل کر ان عوامل نے پلاسٹک کے استعمال اور فضلے کی پیداوار میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔رپورٹ میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ خطے میں پلاسٹک کے استعمال کا 62 فیصد سے زائد حصہ پیکیجنگ سے منسلک ہے، جس کا بیشتر حصہ سنگل یوز ہوتا ہے اور اکثر دریاؤں اور سمندروں میں کوڑے کے طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ پاکستان، اپنے پڑوسی ممالک کی طرح، پلاسٹک کے فضلے کے انتظام میں زبردست چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگرچہ پاکستان کا خطے میں پلاسٹک کے فضلے کے اخراج کی سب سے کم شرح ہے، لیکن ملک کا ناکافی کچرا جمع کرنے کا انفراسٹرکچر اور غیر رسمی فضلہ انتظامیہ کے نظام پر انحصار بڑی رکاوٹیں ہیں۔ غیر رسمی شعبہ، جس میں کچرا چننے والے اور چھوٹے پیمانے کے ری سائیکلرز شامل ہیں، فضلہ کے بحران کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن یہ غیر منظم اور غیر منضبط انداز میں کام کرتا ہے، جس سے اس کی مؤثریت محدود ہو جاتی ہے۔ہندوکش ہمالیائی خطہ ایک اہم علاقہ ہے جہاں پلاسٹک کی آلودگی کے اثرات شدت سے محسوس کیے جاتے ہیں۔ یہ خطہ، جو اہم سرحد پار دریاؤں کا منبع ہے، پلاسٹک کی وجہ سے بڑھتی ہوئی آلودگی کا شکار ہے، جو سرحدوں کے پار بہتے ہوئے ماحولیاتی نظاموں اور زیریں علاقوں کی کمیونٹیز میں تباہی پھیلاتے ہیں۔ ان آبی نظاموں کی بگاڑ نہ صرف حیاتیاتی تنوع کے لیے خطرہ ہے بلکہ ان لاکھوں لوگوں کی معاش اور صحت کو بھی متاثر کرتی ہے جو ان دریاؤں پر پینے کے پانی، زراعت اور ماہی گیری کے لیے انحصار کرتے ہیں۔پلاسٹک کی آلودگی کی سرحد پار نوعیت کے پیش نظر، رپورٹ بجا طور پر علاقائی تعاون کا مطالبہ کرتی ہے۔ جنوبی ایشیائی ممالک کو سیاسی دشمنیوں کو پس پشت ڈال کر اس مشترکہ ماحولیاتی خطرے سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ خطے کی حکومتوں کو اس رپورٹ کے نتائج کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور پلاسٹک کی آلودگی سے نمٹنے کے لیے اپنی کوششوں کو دوبارہ شروع کرنا چاہیے۔ اس میں نہ صرف اندرون ملک فضلہ انتظامیہ کے نظام کو مضبوط بنانا شامل ہے بلکہ فضلہ کو کم کرنے کے مقصد سے علاقائی اقدامات میں سرگرمی سے حصہ لینا بھی شامل ہے۔ ہندوکش ہمالیائی خطے کے دریاؤں کی صحت اور ان پر انحصار کرنے والے لاکھوں لوگوں کا دارومدار اس بات پر ہے کہ یہ قومیں کتنی مؤثر طریقے سے تعاون کر سکتی ہیں۔