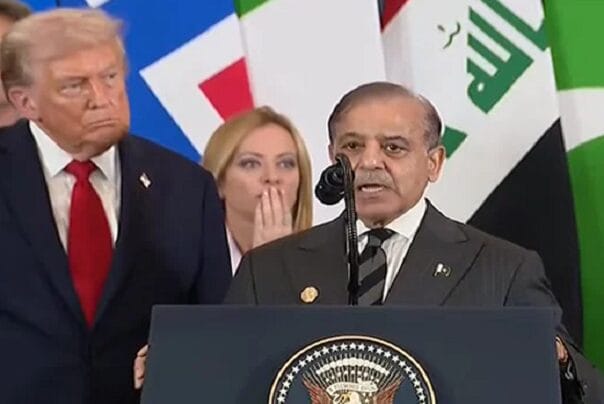پاکستان کی 26ویں آئینی ترمیمی بل، جو وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی قیادت میں موجودہ حکومت نے پیش کیا، ملک کی عدلیہ میں اختیارات کے توازن کے حوالے سے جاری مباحثے میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ یہ ترمیم عدلیہ کے بنیادی ڈھانچے میں گہرائی سے تبدیلیاں لانے کا ارادہ رکھتی ہے، خاص طور پر چیف جسٹس آف پاکستان (چیف جسٹس) کی تقرری اور عدالتی بینچوں کی تشکیل کے طریقہ کار کو از سر نو ترتیب دینے کے لیے۔ یہ اصلاحات شفافیت اور جوابدہی کو فروغ دینے کے نام پر پیش کی گئی ہیں، لیکن ان کے ساتھ سیاسی اور عوامی سطح پر بڑی بحثیں بھی سامنے آئی ہیں جو عدالتی خود مختاری اور اس کی آزاد حیثیت کے بارے میں سوالات اٹھا رہی ہیں۔
اس آئینی ترمیم کا مرکزی نقطہ چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری کے طریقہ کار میں تبدیلی ہے۔ روایتی طور پر، سپریم کورٹ کا سب سے سینئر جج خود بخود چیف جسٹس بن جاتا تھا، جو ایک سادہ اور واضح نظام تھا۔ تاہم، ترمیم میں اس سنیارٹی کی بنیاد پر ہونے والی تقرری کو تبدیل کرنے کی تجویز دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس کا انتخاب سپریم کورٹ کے تین سینئر ترین ججوں میں سے کیا جائے گا۔ اس تبدیلی کا مقصد یہ ہے کہ تقرری کے عمل میں زیادہ لچک اور انتخاب کی گنجائش پیدا کی جائے تاکہ چیف جسٹس کا عہدہ صرف سینیارٹی کی بنیاد پر نہ دیا جائے بلکہ قابلیت اور عدالتی تجربے کو بھی مدنظر رکھا جائے۔
یہ تجویز اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پیش کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہی ہمیشہ اس عہدے کے لیے سب سے موزوں امیدوار نہیں ہوتے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سب سے سینئر جج کی جگہ دوسرے ججز اس عہدے کے لیے زیادہ اہل ہوں۔ یہ تجویز اس بات کو اجاگر کرتی ہے کہ عدالتی تقرریوں میں میرٹ اور قابلیت کا عمل دخل ہونا چاہیے، اور محض سنیارٹی کی بنیاد پر تقرریوں سے گریز کیا جانا چاہیے۔
ترمیم کے مطابق، چیف جسٹس کی تقرری کے لیے ایک خاص پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے گی جس میں 12 ارکان شامل ہوں گے اور اس کمیٹی میں حکومت اور حزب اختلاف کے مساوی ارکان شامل ہوں گے۔ یہ کمیٹی قومی اسمبلی کے 8 اور سینیٹ کے 4 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ کمیٹی چیف جسٹس کے عہدے کے لیے ایک امیدوار کو دو تہائی اکثریت سے منتخب کرے گی اور اس نام کو وزیراعظم کے سامنے پیش کرے گی، جو پھر اس کی حتمی منظوری دیں گے۔
وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے مطابق، اس ترمیم کا بنیادی مقصد عدالتی تقرریوں کے عمل میں شفافیت کو فروغ دینا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے عدالتی تقرریوں میں سیاسی وابستگیوں اور جانبداری کے الزامات کا خاتمہ ہوگا، جو پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اکثر سامنے آتے رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے بھی اس بات پر زور دیا کہ یہ اصلاحات عدلیہ کو زیادہ متوازن اور شفاف بنانے میں معاون ثابت ہوں گی۔
چھبیسویں آئینی ترمیم کا ایک اور اہم پہلو چیف جسٹس کی مدت کو تین سال تک محدود کرنے کی تجویز ہے، یا ان کی 65 سال کی عمر تک، جو بھی پہلے آئے۔ اس کا مقصد عدلیہ میں قیادت کے تسلسل اور استحکام کو یقینی بنانا ہے۔ موجودہ نظام میں چیف جسٹس کی مدت ان کی تقرری کے وقت عمر پر منحصر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کچھ چیف جسٹس صرف چند مہینے ہی اپنے عہدے پر رہ پاتے ہیں۔ یہ صورتحال اکثر عدالتی انتظامی معاملات میں پیچیدگی پیدا کرتی ہے۔
حامیوں کا کہنا ہے کہ ایک مقررہ مدت سے عدلیہ کے اندر طویل المدتی منصوبہ بندی کو فروغ ملے گا اور عدالتی قیادت میں اچانک تبدیلیوں سے پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال کا خاتمہ ہوگا۔ ان کے خیال میں، یہ تبدیلی عدالتی ادارے کے استحکام کو بڑھائے گی اور مختلف ادوار میں مختلف چیف جسٹسز کے تحت عدلیہ کے کام کرنے کے انداز میں نمایاں فرق پیدا نہیں ہونے دے گی۔
تاہم، ناقدین کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس کی مدت کی پابندی عدلیہ کی خود مختاری کو محدود کر سکتی ہے اور سیاسی مداخلت کا خطرہ بڑھا سکتی ہے۔ ان کے مطابق، اس سے حکومتوں کو موقع مل سکتا ہے کہ وہ چیف جسٹس کی تقرری کے وقت سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور اس عہدے کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کریں۔ حزب اختلاف کی جماعتوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ مستقبل میں حکومتیں ایسی ترمیمات کو استعمال کرکے عدلیہ پر اپنا کنٹرول مضبوط کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں۔
چیف جسٹس کی تقرری کے طریقہ کار میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ 26ویں ترمیم میں عدالتی بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے بھی اصلاحات پیش کی گئی ہیں۔ موجودہ نظام کے تحت، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں بینچوں کی تشکیل کا اختیار مکمل طور پر چیف جسٹس کے پاس ہوتا ہے۔ تاہم، اس نئی ترمیم میں تجویز کیا گیا ہے کہ بینچوں کی تشکیل کا اختیار جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو دیا جائے، اور اس کمیشن میں حکومت اور حزب اختلاف دونوں کا کردار شامل کیا جائے۔
نئے مجوزہ نظام کے تحت، جوڈیشل کمیشن میں چیف جسٹس کے ساتھ سپریم کورٹ کے چار سینئر ججز، قومی اسمبلی اور سینیٹ کے دو دو ارکان، وزیر قانون اور اٹارنی جنرل آف پاکستان شامل ہوں گے۔ یہ وسیع تر نمائندگی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کی گئی ہے کہ عدالتی بینچوں کی تشکیل کا عمل صرف عدلیہ کے ہاتھ میں نہ رہے، بلکہ اس میں عوامی نمائندوں کی بھی شمولیت ہو، تاکہ اس عمل میں شفافیت اور جوابدہی کو فروغ ملے۔
تاہم، اس تجویز پر مختلف آراء سامنے آئی ہیں۔ اس ترمیم کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اس سے عدلیہ کے اندر زیادہ شفاف اور جوابدہ نظام تشکیل دیا جا سکے گا اور عدلیہ کو جمہوری عمل سے علیحدہ رہنے کے بجائے عوامی نمائندوں کی تجاویز کا فائدہ ملے گا۔ ان کے مطابق، یہ اصلاحات عدالتی بینچوں کی تشکیل میں زیادہ توازن اور عوامی مفاد کو یقینی بنائیں گی۔
دوسری جانب، ناقدین کا خیال ہے کہ عدالتی بینچوں کی تشکیل میں حکومت اور حزب اختلاف کی شمولیت سے عدلیہ کی خود مختاری پر اثر پڑ سکتا ہے اور اس سے عدالتی فیصلوں میں سیاسی مفادات کا عمل دخل بڑھ سکتا ہے۔ ان کے مطابق، آئینی اور سیاسی نوعیت کے مقدمات میں عدالتی بینچوں کی تشکیل میں سیاسی مداخلت سے عدالتی فیصلوں پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے۔
چھبیسویں آئینی ترمیم کا اعلان ہونے کے بعد سے یہ مسئلہ سیاسی طور پر بہت زیادہ متنازعہ بن چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، جو کہ اس وقت حزب اختلاف کی بڑی جماعت ہے، نے اس ترمیم کی سخت مخالفت کی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر علی خان نے اس ترمیم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت اس بل پر ووٹنگ میں حصہ نہیں لے گی۔ تحریک انصاف نے الزام لگایا ہے کہ بل کو جلد بازی میں اور بغیر مناسب مشاورت کے پیش کیا گیا ہے، اور ان کے ارکان کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔
تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے مزید مشاورت کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ ایسی اہم آئینی تبدیلیاں کرتے وقت سیاسی جماعتوں اور عوامی نمائندوں سے بھرپور رائے لی جانی چاہیے۔ ان کے مطابق، یہ اصلاحات پاکستان کی جمہوریت اور عدلیہ کی خود مختاری پر دیرپا اثرات مرتب کر سکتی ہیں، اس لیے اس پر جلدبازی سے گریز کیا جانا چاہیے۔
گوہر علی خان نے جمعیت علمائے اسلام (ف) کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی کوششوں کو تسلیم کیا جنہوں نے اس بل پر مذاکرات میں مدد فراہم کی، لیکن انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف اس وقت تک اس ترمیم کی حمایت نہیں کر سکتی جب تک کہ اس پر مزید غور و خوض نہ کیا جائے۔ تحریک انصاف کا ووٹنگ سے اجتناب کرنے کا فیصلہ، جبکہ وہ پارلیمانی سیشنز میں شریک رہے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان اس معاملے پر گہری تقسیم موجود ہے۔
پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب عدلیہ پر عوامی اور سیاسی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ عدلیہ پر سیاسی مفادات کے اثرات اور اس کے جمہوری اصولوں کو برقرار رکھنے کے حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس ترمیم کے نتیجے میں چیف جسٹس کی تقرری اور عدلیہ کی قیادت میں مستقل تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں۔
اگر یہ اصلاحات کامیابی سے نافذ کی جاتی ہیں تو ان سے شفافیت میں اضافہ اور چیف جسٹس کی تقرری کے عمل کو زیادہ متوازن بنایا جا سکتا ہے۔
پاکستان میں انسانی حقوق کا بحران: ادارہ جاتی خامیاں اور فوری اصلاحات
پاکستان انسانی حقوق کے تحفظ اور فروغ کے حوالے سے ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی کی حالیہ جائزہ رپورٹ نے ملک میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر شدید تنقید کی ہے۔ اس رپورٹ میں مختلف قسم کی زیادتیوں کو اجاگر کیا گیا ہے، جن میں سیاسی طور پر متحرک افراد پر ظلم، خواتین اور بچوں کے خلاف تشدد، جبری تبدیلی مذہب، اور ماورائے عدالت قتل شامل ہیں۔ اگرچہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کئی سالوں سے جاری ہیں، مگر اس رپورٹ میں ان مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔
پاکستان میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کا ایک اہم پہلو سیاسی طور پر متحرک افراد پر ظلم و ستم اور جبری گمشدگیوں کا سلسلہ ہے۔ مختلف حکومتوں نے آزادیوں کی پامالی میں اپنا کردار ادا کیا ہے، لیکن خاص ریاستی اداروں نے خاص طور پر جبری گمشدگیوں جیسے جرائم میں ملوث کردار ادا کیا ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا جیسے صوبوں میں، وہ افراد جو ریاستی ظلم کے خلاف پرامن احتجاج کرتے ہیں یا حکومت مخالف نظریات رکھتے ہیں، شدید کریک ڈاؤن کا سامنا کرتے ہیں۔ ریاست کا ایسے اختلافات کو دبانے کا طریقہ کار اکثر سخت اور ظالمانہ ہوتا ہے، جس سے ایک خوف کا ماحول پیدا ہوتا ہے اور جائز سیاسی اظہار پر پابندیاں لگتی ہیں۔
جبری گمشدگیاں پاکستان کے انسانی حقوق کے ریکارڈ پر ایک سیاہ داغ ہیں۔ سیکڑوں شہری، خاص طور پر محروم علاقوں سے، لاپتہ ہو چکے ہیں، اور ان کے خاندان ان کی موجودگی سے لاعلم ہیں۔ اقوام متحدہ کی کمیٹی نے اس عمل پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے، اور کہا ہے کہ ریاست کا خاموش رہنا یا اس میں ملوث ہونا قانون کی حکمرانی کی بنیادی خلاف ورزی کی عکاسی کرتا ہے۔ عالمی ادارے پاکستان پر زور دیتے رہے ہیں کہ وہ جبری گمشدگیوں کے خلاف قانون سازی کرے اور سیکیورٹی اداروں کو جوابدہ بنائے، مگر اس سلسلے میں بہت کم پیشرفت ہوئی ہے۔
پاکستان میں مذہبی اقلیتیں مسلسل دباؤ اور ظلم کا شکار ہیں، جن میں سب سے نمایاں بلاسفیمی (توہینِ مذہب) قوانین کا غلط استعمال اور جبری تبدیلی مذہب شامل ہیں۔ توہینِ مذہب کے الزامات، جو اکثر کمزور ثبوت یا ذاتی دشمنیوں کی بنیاد پر لگائے جاتے ہیں، ملزم کے لیے تباہ کن نتائج پیدا کرتے ہیں، جنہیں اکثر ہجوم کے تشدد یا طویل قید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جائزہ رپورٹ نے حکومت کے 74 جبری تبدیلی مذہب کے کیسز کو بہت کم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ عیسائی، ہندو اور احمدی کمیونٹیز جیسے گروہوں کے لیے ریاست کا مذہبی انتہاپسندوں سے انہیں بچانے میں ناکامی ایک سنگین آئینی خلاف ورزی ہے۔
توہینِ مذہب کے قوانین کا غلط استعمال مذہبی آزادیوں کے تحفظ میں ریاست کی ناکامی کی علامت ہے۔ یہ قوانین اقلیتوں کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جس سے وہ قانونی ظلم اور ہجوم کے تشدد کے لیے کھلے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔
پاکستان میں خواتین اور بچوں کی صورتحال بھی انتہائی نازک ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ نے خواتین کے خلاف بے تحاشہ تشدد کو اجاگر کیا، اور بتایا کہ ملک میں ہر دو منٹ میں ایک ریپ کا واقعہ پیش آتا ہے، جبکہ سزا کی شرح محض 3 فیصد ہے۔ یہ انتہائی کم سزا کی شرح پاکستان کے عدالتی نظام میں نظامی خامیوں کی عکاسی کرتی ہے، جو بدعنوانی، نااہلی اور صنفی تعصب کا شکار ہے۔ انصاف کے متلاشی خواتین کو اکثر ناقابلِ برداشت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں پولیس کی بے حسی اور معاشرتی دباؤ شامل ہیں، جو انہیں مزید استحصال کا شکار بناتا ہے۔
پاکستان میں انسانی حقوق کے بحران کی جڑ میں حکومت اور عدالتی نظام میں گہرے ساختی مسائل موجود ہیں۔ خاص طور پر خواتین کے خلاف بڑھتے ہوئے جرائم کا براہ راست تعلق ان کمزوریوں سے ہے۔ پاکستان کا فوجداری انصاف کا نظام نہ صرف غیر مؤثر بلکہ غیر منصفانہ بھی ہے، جو طاقتور افراد کو جوابدہی سے بچنے کی اجازت دیتا ہے، جبکہ محروم طبقے خاموشی سے ظلم کا شکار ہوتے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں بدعنوانی اور نااہلی کو حل کرنے میں ناکامی صورتحال کو مزید خراب کرتی ہے، جس سے سزا سے بچنے کا کلچر فروغ پاتا ہے۔
یہ ٹوٹا ہوا نظام اس بات کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ ریاست انتہا پسند مذہبی عناصر پر قابو پانے میں ناکام ہے۔ انتہا پسند گروہ اکثر ریاست کی جانب سے مزاحمت کے بغیر بڑے اثر و رسوخ کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اقلیتوں اور خواتین کے خلاف تشدد نہ صرف برداشت کیا جاتا ہے بلکہ بعض صورتوں میں اس کی حمایت بھی کی جاتی ہے۔ جب تک پاکستان انتہا پسندی کی بنیادی وجوہات کو حل نہیں کرتا اور اپنی سیکیورٹی اپریٹس میں اصلاحات نہیں لاتا، خوف اور تشدد کی یہ ثقافت جاری رہے گی۔
پاکستان کے اقتصادی مسائل یقیناً سنگین ہیں، لیکن حکومت کی تمام توجہ انہی مسائل پر مرکوز نہیں ہونی چاہیے۔ ریاست کی انسانی حقوق سے غفلت نے ایک وسیع تر معاشرتی مایوسی کو جنم دیا ہے جس نے ملک کی ترقی اور استحکام کو متاثر کیا ہے۔ جیسا کہ اقوام متحدہ کے جائزے میں واضح کیا گیا ہے، انسانی حقوق کو اقتصادی اصلاحات کے ساتھ ترجیح دینا ہی حقیقی پیش رفت کا باعث بن سکتا ہے۔
انسانی حقوق کے بحران کو حل کرنے کے لیے پاکستان کو ایک جامع حکمت عملی اپنانی ہوگی۔ سب سے پہلے، ریاست کو اپنے قانونی اور ادارہ جاتی فریم ورک کو مضبوط کرنا ہوگا تاکہ تمام شہریوں، خاص طور پر سب سے زیادہ کمزور افراد کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے۔ اس میں جبری گمشدگیوں کو جرم قرار دینے کے لیے قانون سازی کرنا، توہینِ مذہب کے قوانین میں اصلاحات لانا تاکہ ان کے غلط استعمال کو روکا جا سکے، اور صنفی بنیاد پر ہونے والے تشدد کے متاثرین کو انصاف تک رسائی فراہم کرنا شامل ہے۔
اس کے علاوہ، حکومت کو فوجداری انصاف کے نظام میں موجود ساختی خامیوں کو دور کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ اس کے لیے نہ صرف بدعنوانی اور نااہلی سے نمٹنا ضروری ہے بلکہ یہ بھی یقینی بنانا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے خواتین اور بچوں کے خلاف تشدد کے واقعات کو حساسیت اور ہنگامی بنیادوں پر نمٹائیں۔ ریپ اور دیگر صنفی بنیاد پر ہونے والے جرائم کے لیے کم سزا کی شرح موجودہ نظام پر عوامی اعتماد کی کمی کو ظاہر کرتی ہے، اور اس کو بحال کرنے کے لیے فوری اصلاحات کی ضرورت ہے۔
کسی بھی انسانی حقوق کی اصلاح کا ایک اہم پہلو احتساب ہے۔ ریاست کو منتخب نمائندوں کو ان کے حلقوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے جوابدہ بنانا چاہیے اور یہ یقینی بنانا چاہیے کہ پالیسیز بین الاقوامی انسانی حقوق کے معیارات کے مطابق ہوں۔ اکثر، انسانی حقوق کو ایک خیرات کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو عوام کو دی جاتی ہے، جبکہ حقیقت میں یہ بنیادی حقوق ہیں جن کا احترام ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔
پاکستان ایک دوراہے پر کھڑا ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی کا جائزہ اس بات کی واضح یاد دہانی ہے کہ فوری اصلاحات کی ضرورت ہے، نہ صرف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے فوری مسائل کو حل کرنے کے لیے بلکہ طویل مدتی استحکام اور ترقی کے لیے بھی بنیاد رکھنے کے لیے۔ ریاست کو تسلیم کرنا ہوگا کہ انسانی حقوق کوئی ثانوی مسئلہ نہیں ہیں بلکہ حکومت اور جمہوریت کا ایک اہم ستون ہیں۔
جامع اصلاحات کے ذریعے، فوجداری انصاف کے نظام میں نظامی خامیوں کو دور کر کے، اور منتخب نمائندوں کو جوابدہ بنا کر، پاکستان اپنے انسانی حقوق کے ریکارڈ کو بہتر بنانا شروع کر سکتا ہے۔ تاہم، اس کے لیے نہ صرف سیاسی عزم بلکہ اس بات میں بھی ایک بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہوگی کہ ریاست اپنے شہریوں کے ساتھ تعلق کو کیسے دیکھتی ہے۔ صرف انسانی حقوق کو ترجیح دے کر ہی پاکستان ایک ایسا مستقبل تشکیل دے سکتا ہے جو منصفانہ، جامع، اور تمام لوگوں کے لیے محفوظ ہو۔