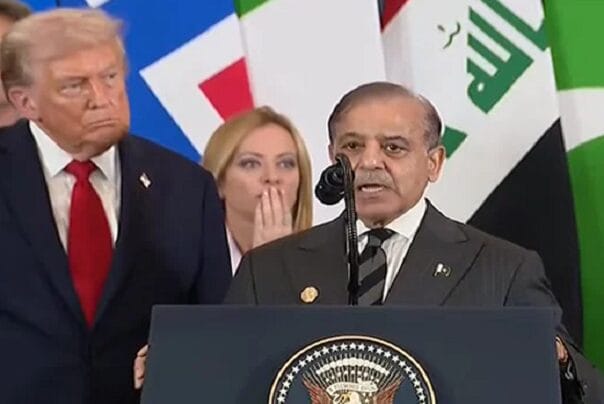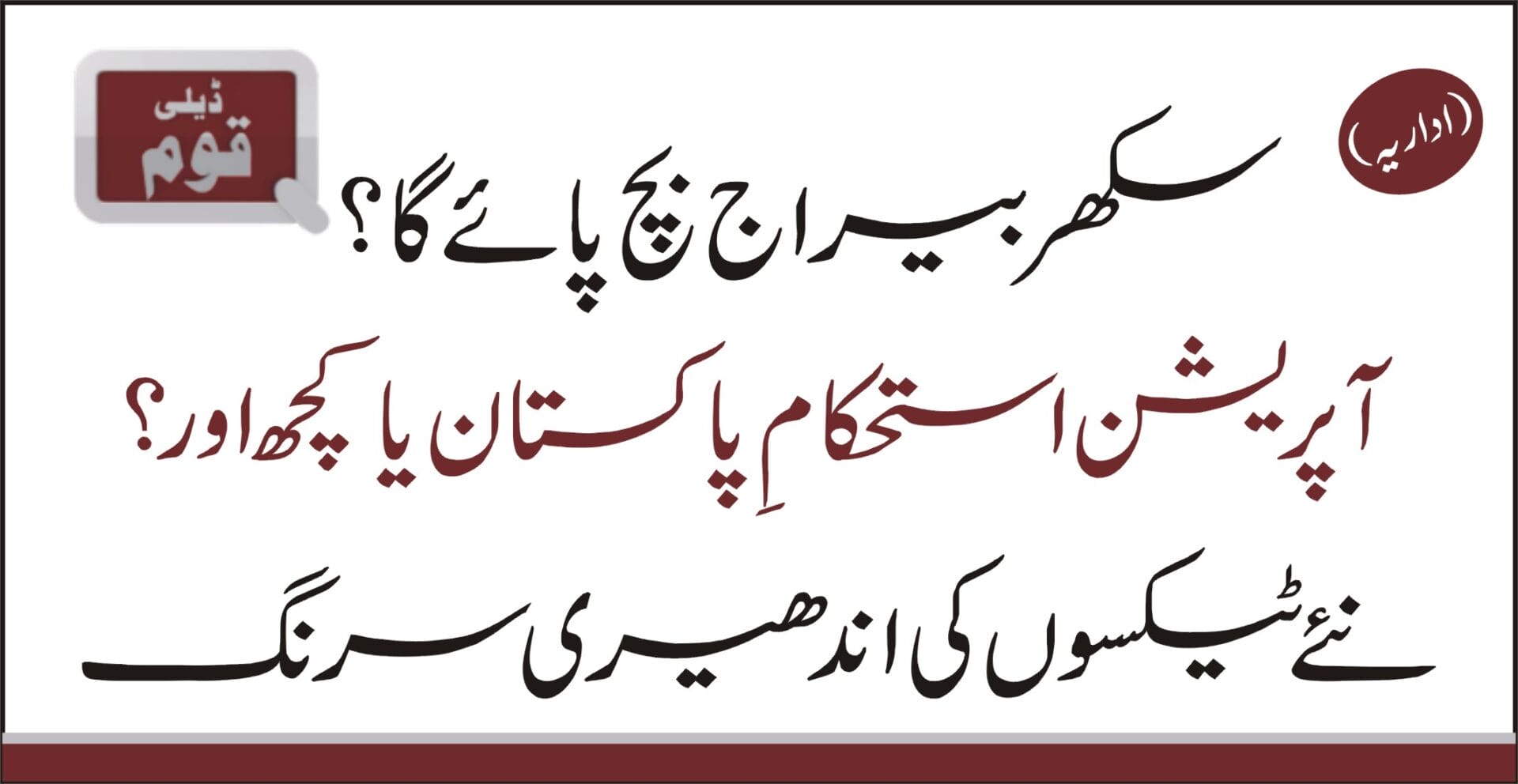جون 20 کو سکھر بیراج کے گیٹ نمبر 47 کے اچانک گرنے سے سندھ کے آبپاشی نظام میں بحران پیدا ہوگیا۔ سات نہروں میں پانی کی تقسیم روکنی پڑی جبکہ صوبے میں خریف کی فصلوں کے لئے آبپاشی کی طلب عروج پر تھی۔ اس واقعے کے بعد کاشتکاروں میں بے چینی پھیل گئی ہے کیونکہ ان کی چاول، کپاس اور گنے کی فصلوں کو پانی کی ضرورت ہے۔
سکھر بیراج سندھ کی زرعی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو صوبے کی 80 فیصد زرعی زمین کو سیراب کرتا ہے۔ حکام چینی ماہرین کی مدد سے بحران کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پہلے سے ہی بیراج کی بحالی پر کام کر رہے تھے۔ آبپاشی کے وزیر نے بھی معاملے کی تحقیقات کے لئے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔
سکھر بیراج کو آبپاشی انجینئرنگ کا شاہکار مانا جاتا ہے، لیکن 1932 میں تعمیر ہونے کے بعد سے اس نے کئی تکنیکی چیلنجز کا سامنا کیا ہے۔ بیراج نے نہ صرف ایک بڑی زرعی معیشت کو فروغ دیا بلکہ سندھ کے سماجی و سیاسی ڈھانچے کو بھی تشکیل دیا۔
برطانوی دور میں مستقل آبپاشی نظام کی آمد سے پہلے، سندھ میں زراعت پرانے طغیانی نہروں کے ذریعے کی جاتی تھی۔ سالانہ بارش کی اوسط مقدار صرف 100 ملی میٹر جبکہ سالانہ بخارات کی مقدار 2,200 ملی میٹر سے زیادہ ہونے کی وجہ سے بارانی زراعت سے پیداوار نہ ہونے کے برابر تھی۔
برطانوی انجینئرز نے سندھ میں دریائے سندھ پر ایک بیراج کی تجویز پیش کی تاکہ فصلیں اگانے کے لئے دریا کے پانی کو محفوظ کیا جا سکے۔ 1847 میں کرنل والٹر سکاٹ نے سکھر اور روہڑی کے درمیان ایک ڈھانچے کی تجویز دی۔ تاہم، تقریباً چھ دہائیوں تک اس منصوبے کو بمبئی حکام کی منظوری نہیں ملی۔ 1923 میں بمبئی قانون ساز اسمبلی نے آخر کار اس منصوبے کی منظوری دی اور 1932 میں بیراج مکمل ہوا۔
سکھر بیراج میں 66 گیٹس ہیں، ہر ایک کی چوڑائی 60 فٹ (18.2 میٹر) ہے۔ بیراج کے کمیشننگ کے بعد سے ہی تکنیکی مسائل شروع ہو گئے۔ 1938-41 میں کئے گئے ایک ہائیڈرولک ماڈل مطالعے نے حکام کو سلیٹ اخراج کرنے والا تعمیر کرنے اور 10 گیٹس کو مستقل طور پر بند کرنے پر مجبور کیا۔ اس بڑی تبدیلی کی وجہ سے بیراج کی سیلابی گزرگاہ کی صلاحیت 1.5 ملین سے کم ہو کر 0.9 ملین کیوسک رہ گئی۔
تازہ ترین گیٹ کا گرنا سکھر بیراج کی تاریخ میں پہلا واقعہ نہیں ہے۔ 1982 میں گیٹ نمبر 31 بھی گر گیا تھا۔ اس واقعے پر ایک تکنیکی رپورٹ “سکھر بیراج گیٹ نمبر 31 کی ناکامی اور تبدیلی کا پروگرام مطالعہ” نے تفصیل سے تجزیہ کیا۔
سندھ کے آبپاشی محکمہ میں بدعنوانی، نااہلی اور ناقص نگرانی کی تحقیقات بھی ضروری ہیں۔ کسی بھی ڈھانچے کی انجینئرنگ ناکامی بغیر علامات کے نہیں ہوتی۔ ایک مؤثر نگرانی کا نظام بروقت خطرے کی گھنٹی بجا سکتا تھا اور شاید کچھ بروقت اقدامات اس واقعے کو روک سکتے تھے۔
سندھ کے پرانے بیراج ڈھانچے کو بھی بڑی مرمت کی ضرورت ہے۔ سکھر، کوٹری اور گدو بیراج بالترتیب 1932، 1958 اور 1963 میں تعمیر ہوئے تھے۔ عالمی بینک کے مالی تعاون سے سندھ بیراجوں کی بہتری کا منصوبہ بھی نافذ کیا جا رہا ہے جس میں سکھر بیراج کی بحالی اور جدیدیت شامل ہے۔ سکھر اور دیگر بیراجوں کے تمام گیٹس کی فوری تکنیکی جانچ کی جانی چاہئے، خاص طور پر مون سون کے موسم سے پہلے۔ معمول سے ہٹ کر درجہ حرارت اور بارش کی پیش گوئی اضافی نگرانی اور سیلابی انتظام ڈھانچوں کی دیکھ بھال کا مطالبہ کرتی ہے۔
آپریشن استحکامِ پاکستان یا کچھ اور؟
کیا یہ ایک محض ایک تصور/ وژن ہے، غیر واضح پروگرام ہے، یا حقیقی فوجی آپریشن؟ ایک ہفتہ گزر گیا ہے، اور ہم ابھی تک واضح طور پر نہیں جانتے یہ کیا ہے؟ آپریشن عزمِ استحکام اسی طرح کی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے جسے ٹھیک کرنے کے لئے اس کا آغاز ہوا۔ یہ تشویشناک ہے کہ ایک اہم دہشت گردی مخالف اقدام، جسے پرتشدد واقعات میں اضافے کے دوران اعلان کیا گیا تھا، اور وہ اس قدر غیر واضح ہے۔ حکومت نے اس کے حقیقی دائرہ کار اور ارادے کے بارے میں تذبذب کا اظہار کیا ہے اور جہاں اس کے نفاذ کا امکان ہے وہاں کے نمائندوں کی سخت مزاحمت نے اس معاملے پر اور الجھن پیدا کردی ہے۔
نامعلوم سیکورٹی ذرائع نے مقامی میڈیا کو یقین دلایا ہے کہ اس آپریشن کے تحت شہری آبادی کی نقل مکانی نہیں ہوگی اور نہ ہی بڑے پیمانے پر فوجی کارروائی کی جائے گی۔ تو پھر یہ اصل میں کیا ہوگا؟
پاکستان کے سفیر مسعود خان حال ہی میں واشنگٹن میں چھوٹے ہتھیاروں اور جدید سازوسامان کے لئے مدد طلب کر رہے تھے۔ سفیر کی وضاحتوں کے مطابق، اس اقدام کے تین اجزاء ہیں: نظریاتی، معاشرتی اور آپریشنل۔ ان کے مطابق، پہلے دو اجزاء پر کام جاری ہے اور تیسرے پر کام شروع ہونے والا ہے۔ اس تیسرے جزو کے لئے، پاکستان “مضبوط سیکورٹی روابط، انٹیلی جنس تعاون کو بڑھانے، جدید فوجی پلیٹ فارم کی فروخت کی بحالی، اور امریکی اصل دفاعی سازوسامان کی بحالی” کی کوشش کر رہا ہے۔
دفاعی وزیر نے بھی افغانستان میں دہشت گردوں کے تعاقب کے امکان کے بارے میں بات کی ہے۔ یہ دونوں باتیں نہ صرف محدود کارروائیوں کی یقین دہانی سے متصادم ہیں بلکہ وزیر دفاع خواجہ آصف کے حالیہ بیان سے بھی متضاد ہیں کہ پاکستان اس اقدام کے لئے واشنگٹن سے مدد نہیں مانگ رہا۔ حکومت کے ارادوں اور عوامی بیانات کے درمیان اتنا واضح تضاد کیوں ہے؟ حکومت کو جواب دینا چاہئے۔
کچھ دیگر تفصیلات معقول معلوم ہوتی ہیں: اسمگلنگ اور سرحد پار دراندازی کی روک تھام اور دہشت گردی سے متعلق جرائم کی پراسیکیوشن کو مضبوط بنانا۔ تاہم، اگر حکومت کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہے تو اسے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ایک مربوط پروگرام کا اشتراک کرنا ہوگا۔ عزمِ استحکام اس وقت تبدیلی کے عمل میں ہے اور کسی بھی پائیدار استحکام کی جستجو کا آغاز ایک مستقل منصوبے سے ہونا چاہئے۔
یہاں پر کچھ سوالات پاکستان کی سویلین اور فوجی قیادت سے بھی بنتے ہیں- حال ہی میں میڈیا میں رپورٹس آئی ہیں کہ وفاقی انٹیلی جنس ایجنسی آئی بی نے سی پیک روٹ اور منصوبوں کی سیکورٹی میں بڑے پیمانے پر نقائص پانے جانے کی نشاندہی پر مبنی ایک خصوصی رپورٹ حکومت کو ارسال کی ہے۔ سی پیک روٹ اور منصوبوں کی سیکورٹی پر اب تک بہت بھاری رقوم خرچ ہوئی ہیں اور وفاقی حکومت نے ان فنڈز کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کا عندیہ دیا تھا، اس پر اب تک کوئی پیش رفت سامنے کیوں نہیں آئی؟ فوجی قیادت نے بلوچستان اور کے پی کے کی سرحدی چیک پوسٹوں سے اسمگلنگ رکوانے کا دعوا کیا تھا لیکن اب تک ایرانی پٹرول، ڈیزل سمیت دیگر اشیاء کی اسمگلنگ میں کوئی حاص کمی دیکھنے کو نہیں ملی، کیوں؟ آخر ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت ، ٹانک میں مقامی پولیس ، ایف سی اور فوجی دستوں کی موجودگی کے باوجود وہاں ٹی ٹی پی، تحریک المجاہدین، داعش خراسان کیسے سرگرم ہوئے اور وہ اب ان اضلاع میں کھلے عام بھتہ وصول کر رہے ہیں، یہاں درجنوں انٹیلی جنس بیسڈ آپریشنوں – آئی بی اوز کا کیا بنا؟ نیشنل ایکشن پلان کو یکساں اور بلا امتیاز نافذ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ ریاستی سویلین و فوجی سیکورٹی اداروں کی کارکردگی پر عوام کا اعتماد کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے؟ حکومت کو عملی نتائج دکھانے ہوں گے تب کہیں جاکر عوام کے اعتماد کو بحال کرایا جاسکے گا۔
نئے ٹیکسوں کی اندھیری سرنگ
حکومت کو آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے لئے اپنے ٹیکس ریونیو کو بڑھانے کی شدید ضرورت ہے، جہاں ایک بڑے پروگرام کی توقع ہے۔ تاہم، آئی ایم ایف قرض کی پائیداری کے لئے زیادہ وسائل یا جی ڈی پی کے مقابلے میں زیادہ ٹیکس آمدن کا مطالبہ کر رہا ہے۔
مسلسل حکومتیں براہ راست ٹیکس بیس کو بڑھانے اور ٹیکس نیٹ سے باہر افراد کو نظام میں لانے میں ناکام رہی ہیں۔ اکثر، براہ راست ٹیکس کو بالواسطہ طریقے سے جمع کیا جاتا ہے۔
ریونیو میں نمایاں اضافے کے لئے، حکومتوں نے ہمیشہ آسان راستہ اختیار کیا ہے: آسانی سے جمع ہونے والے ٹیکس ہدف بنانا۔ اس مقصد کے تحت، انہوں نے ایک پیشکش ٹیکس نظام بنایا، جہاں ٹیکس دہندہ کو اپنی سالانہ آمدنی کا ایک مخصوص فیصد بطور انکم ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے، چاہے اسے نقصان ہو یا منافع۔ اس ٹیکس کو حتمی ذمہ داری سمجھا جاتا تھا اور ایف بی آر کو کتابیں جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔
کاروبار اس نظام سے خوش تھے کیونکہ یہ انہیں ذاتی اور گھریلو اخراجات کو کاروباری اخراجات میں شامل کرنے کی آزادی دیتا تھا۔ مختلف طبقوں کے لئے 0.5 فیصد سے 8 فیصد تک کے مختلف پیشکش ٹیکس کی شرحیں عائد کی گئیں۔
تاہم، اس نظام نے کئی مشکلات اور بگاڑ پیدا کیے۔ آمدنی اور اثاثوں کی تخلیق کے درمیان تعلق قائم کرنا مشکل ہوگیا اور دستاویزات کا فقدان ہوگیا۔
ریاست نے تمام ٹیکس دہندگان کے لئے کم از کم ٹیکس کا تصور بھی پیش کیا۔ یعنی اگر ٹیکس دہندہ سال کے لئے نقصان اٹھاتا ہے، پھر بھی اسے اپنی آمدنی کے ایک فیصد کے مطابق کم از کم ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔
یہ ٹیکس کا طریقہ کار آمدنی پر ٹیکس کے بنیادی تصور کے خلاف ہے، ٹیکس دہندہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس سے شہریوں کو ٹیکس دہندگان کے گروہ میں شامل ہونے سے روکتا ہے۔
سادہ الفاظ میں، یہ ریاست کی طرف سے جبری وصولی ہے۔ مزید برآں، پیشکش ٹیکس کا تصور ختم کردیا گیا اور اسے کم از کم ٹیکس کی شکل دے دی گئی۔
مجموعی ٹیکس نظام رجعتی ہے اور دستاویزات اور احتساب کے اصولوں کے خلاف ہے۔ کم از کم ٹیکس کا تصور ہی کافی ہے کہ خوف پیدا ہو جائے، اور غیر فائلرز کو صرف زیادہ شرحوں پر ٹیکس ادا کر کے چھوٹ دینا، ٹیکس چوروں اور غیر رسمی شعبے کو ٹیکس نیٹ سے باہر رہنے کی اجازت دیتا ہے۔
یہ ایماندار ٹیکس دہندگان کی توہین ہے۔ سرمایہ کاری کی شرح جی ڈی پی کے مقابلے میں پہلے ہی 50 سالوں میں سب سے کم ہے جبکہ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری بھی کم ہو رہی ہے۔
ملک کو برآمدات کی اشد ضرورت ہے لیکن ایک رجعتی ٹیکس نظام، زیادہ سود کی شرحیں اور بڑھتی ہوئی توانائی کے اخراجات بڑے رکاوٹیں ہیں۔
حکومت کو اپنی مالی پالیسی اور ایف بی آر کے رویے پر نظرثانی کرنی چاہئے اگر وہ برآمدی اور پیداواری شعبوں میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا چاہتی ہے۔ ہر آمدنی کو یکساں سلوک ملنا چاہئے اور تمام کے لئے یکساں انکم ٹیکس ہونا چاہئے۔ برآمد کنندگان کو توانائی اور سود کی لاگت میں رعایت کا حق ہو سکتا ہے، لیکن انہیں اپنی آمدنی پر واجب الادا ٹیکس ادا کرنا چاہئے۔