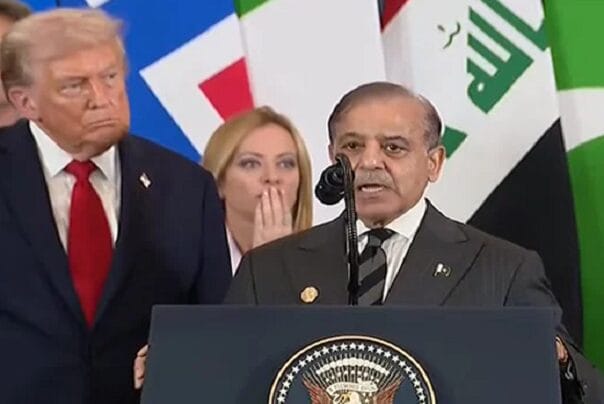بدھ کی رات واشنگٹن کے ریگن نیشنل ایئرپورٹ کے قریب جو حادثہ پیش آیا، وہ محض ایک فضائی سانحہ نہیں بلکہ امریکی پالیسی سازی کی نااہلی اور طاقتور حلقوں کی خودغرضی کا ایک اور مظہر ہے۔ امریکی حکومت اور اس کے قانون ساز جو دنیا بھر میں فضائی تحفظ کے اصولوں کے چیمپئن بنتے ہیں، اپنی ہی دہلیز پر ان اصولوں کو پامال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس حادثے میں، ایک مسافر طیارہ اور ایک فوجی ہیلی کاپٹر آسمان میں اس طرح ٹکرائے، جیسے یہ کوئی منظم فضائی حدود نہیں بلکہ کسی بگڑے ہوئے ٹریفک سگنل کا چوراہا ہو۔یہ حادثہ حیران کن نہیں، کیونکہ ماہرین برسوں سے انتباہ دے رہے تھے کہ واشنگٹن کی فضائی حدود ایک “اڑتا ہوا ٹائم بم” بن چکی ہے۔ لیکن امریکی پالیسی سازوں کے لیے جب بھی انتخاب ہوتا ہے کہ حفاظت کو ترجیح دی جائے یا اپنے سیاسی مفادات کو، تو وہ ہمیشہ دوسرا راستہ چنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال فضائی حدود مزید بھری جا رہی ہیں، مزید پروازوں کو اجازت دی جا رہی ہے، اور ہر ممکن طریقے سے اس ایئرپورٹ کو کھچا کھچ بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ واشنگٹن کے بااثر افراد کو سہولت مل سکے، چاہے عام مسافروں کی جان دائو پر ہی کیوں نہ لگے۔واشنگٹن کے ریگن نیشنل ایئرپورٹ کے آسمانوں میں روزانہ 800 سے زیادہ پروازیں اڑتی ہیں، جبکہ یہ ایئرپورٹ اصل میں صرف 600 پروازوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی معیشت رکھنے والے امریکہ میں، جہاں ہر چیز کو ضابطوں، قوانین اور سیکیورٹی پروٹوکولز کے پیچیدہ جال میں لپیٹ دیا جاتا ہے، وہاں یہ ایئرپورٹ ایک کھلی چھوٹ کا نمونہ بنا ہوا ہے۔کانگریس کے ارکان، جو ملک کی بھلائی کے نام پر قانون سازی کرتے ہیں، خود ہی اس ایئرپورٹ پر دباؤ ڈالنے کی پالیسی بنا رہے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے تاکہ یہ سیاستدان اپنے آبائی ریاستوں کے مختصر مگر آرام دہ” دورے کر سکیں، بغیر اس کے کہ انہیں کسی اور ایئرپورٹ پر اتر کر سفر کا تھوڑا سا تکلیف دہ حصہ برداشت کرنا پڑے۔ عوام کو بھلے لمبی قطاروں، طویل تاخیر اور خطرناک حد تک بھرے ہوئے فضائی راستوں کا سامنا کرنا پڑے، مگر کانگریس کے معزز اراکین کو سہولت میسر ہونی چاہیے!یہی وجہ ہے کہ جب بھی ماہرین نے خبردار کیا کہ ریگن ایئرپورٹ کی گنجائش ختم ہو چکی ہے، تو کانگریس نے ان انتباہات کو ردی کی ٹوکری میں ڈال کر مزید پروازوں کی منظوری دے دی۔ کیونکہ آخر میں، سیاستدانوں کی خوشنودی ایوی ایشن سیفٹی سے زیادہ قیمتی سمجھی جاتی ہے۔یہ حادثہ نہ تو پہلا ہے اور نہ ہی آخری ہوگا۔ 2013 میں، ایک پائلٹ نے ایک سرکاری رپورٹ میں لکھا تھا:میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کون سا ایسا ضروری کام ہو سکتا ہے کہ ان ہیلی کاپٹروں کو سینکڑوں مسافروں والے ایئر لائنر کے راستے میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے!”یہ الفاظ کسی عام مسافر کے نہیں، بلکہ ایک پیشہ ور پائلٹ کے تھے جو روزانہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس غیر محفوظ فضائی حدود سے گزرتا تھا۔ اور یہ صرف ایک پائلٹ کی شکایت نہیں، درجنوں رپورٹس میں یہی خدشات بیان کیے جا چکے ہیں، مگر ہر دفعہ وہی جواب دیا گیا: “ہم اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں” – اور پھر کچھ بھی نہیں بدلا۔ریگن نیشنل ایئرپورٹ کے آسمانوں میں صرف تجارتی طیارے نہیں اڑتے، بلکہ فوجی اور سرکاری طیارے بھی مستقل گشت کرتے ہیں۔ بلیک ہاک ہیلی کاپٹر، جنہیں عموماً جنگی زونز میں دیکھا جاتا ہے، یہاں واشنگٹن ڈی سی میں بھی عام نظر آتے ہیں۔ پینٹاگون کے اعلیٰ عہدیدار، سیاستدان، اور دیگر وی آئی پی شخصیات ان ہیلی کاپٹروں میں سفر کرتی ہیں، اور اکثر ان کی پروازیں کسی بھی تجارتی فلائٹ کے بالکل قریب سے گزرتی ہیں۔بدھ کی رات بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ایک عام مسافر طیارہ، جس میں درجنوں لوگ اپنی روزمرہ زندگی کے کاموں میں مصروف تھے، ایک فوجی ہیلی کاپٹر سے ٹکرا گیا، کیونکہ واشنگٹن کی فضائی حدود میں غلطی کی گنجائش نہ ہونے کے برابر ہے۔ریگن نیشنل ایئرپورٹ کا مسئلہ صرف گنجان فضائی ٹریفک تک محدود نہیں۔ یہ ایئرپورٹ، جو درحقیقت ایک “سیاسی کھلونا” بن چکا ہے، ان طاقتور لوگوں کے لیے مخصوص سہولت فراہم کرتا ہے، جو قانون سازی کرتے ہیں۔سن 1860ء کی دہائی میں، جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ واشنگٹن کے لیے ایک بڑا اور محفوظ ایئرپورٹ ہونا چاہیے، تو ڈلس بین الاقوامی ایئرپورٹ بنایا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ بڑی اور دور دراز کی پروازیں وہاں سے روانہ ہوں، جبکہ ریگن نیشنل صرف چھوٹی پروازوں کے لیے مخصوص رہے۔ لیکن وقت کے ساتھ، سیاسی اثرو رسوخ اور لابنگ کے نتیجے میں اس ایئرپورٹ کو ایک خصوصی استثنیٰ” مل گیا۔مرحوم سینیٹر جان مکین نے، مثال کے طور پر، ریگن نیشنل سے فینکس تک نان اسٹاپ پرواز کے لیے زور دیا، تاکہ وہ اپنے گھر جلدی پہنچ سکیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے خود اس پرواز کو استعمال کرنے سے گریز کیا تاکہ یہ تاثر نہ ملے کہ یہ فیصلہ ذاتی فائدے کے لیے تھا۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہر نیا قانون، ہر نئی پالیسی، اور ہر نیا استثنیٰ بالآخر انہی طاقتور شخصیات کے فائدے میں جاتا ہے، جن کے لیے عوامی تحفظ” محض ایک نعرہ ہے۔ریگن نیشنل ایئرپورٹ کی گنجان فضائی حدود ایک کھلی حقیقت ہے۔ بدھ کی رات کا حادثہ بھی ایک واضح انتباہ ہے کہ اگر کوئی ٹھوس قدم نہ اٹھایا گیا تو مستقبل میں مزید جانیں ضائع ہو سکتی ہیں۔مگر کیا امریکی حکومت واقعی اس حادثے سے کچھ سیکھے گی؟ کیا واشنگٹن کے طاقتور حلقے اپنی عادتیں بدلیں گے؟ تاریخ کے تجربے سے تو یہی لگتا ہے کہ کچھ نہیں بدلے گا۔ ایک مختصر سی تحقیقات ہوگی، کچھ رپورٹس لکھی جائیں گی، چند ماہرین” ٹی وی پر آ کر تبصرے کریں گے، اور پھر سب کچھ ویسے ہی چلتا رہے گا جیسے پہلے چل رہا تھا۔جب تک پالیسی ساز اپنے مفادات کو عوامی تحفظ پر فوقیت دیتے رہیں گے، تب تک ایسے حادثات ہوتے رہیں گے۔ آخر میں، وہی عام شہری قیمت چکاتے رہیں گے، جو کسی کانگریس مین کے آرام دہ سفر کے لیے اپنی جان دائو پر لگا کر سفر کر رہے ہوتے ہیں۔تو کیا یہ حادثہ آخری ہوگا؟ بالکل نہیں۔ جب تک واشنگٹن کے آسمانوں میں طاقتور لوگوں کے مفادات اڑ رہے ہیں، عام شہریوں کی زندگیاں خطرے میں ہی رہیں گی۔
پاکستان کس سمت جا رہا ہے؟
پاکستان میں پالیسی سازوں کو جلد یا بدیر خود سے یہ سوال کرنا ہوگا: ان کی پالیسیوں نے ملک کے 24 کروڑ عوام کے لیے کیا حاصل کیا ہے؟ کیا وہ مقاصد، جن کے لیے ریاست کی بنیادیں ہلا دی گئیں اور عوام پر زبردستی ایک نیا سماجی معاہدہ تھوپا گیا، جمہوری سیاسی عمل کے ذریعے حاصل نہیں کیے جا سکتے تھے؟سیاسی عدم استحکام کے نتیجے میں ہونے والے معاشی بحران پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے اس کھیل میں عوام کو بے شمار اضافی قیمتیں چکانی پڑی ہیں، جن کا حساب ہونا ابھی باقی ہے۔ اور صورتحال سدھرنے کے بجائے مسلسل بگڑتی جا رہی ہے۔نئے قوانین کے ذریعے آزادیٔ اظہار پر قدغنیں، ڈیجیٹل معیشت کی تباہی، اور عدلیہ کے بحران جیسے معاملات اس حقیقت کی واضح مثالیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم کب اپنی سمت درست کریں گے؟ہمارے پالیسی ساز اگر صرف ٹھوس اور براہِ راست نتائج پر توجہ دیتے ہیں، تو انہیں یورپی یونین کے نمائندے کے حالیہ انتباہ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ 2014 سے، پاکستان کو یورپی منڈیوں میں خصوصی رعایت حاصل ہے، جس کے تحت ہماری برآمدات، خاص طور پر ٹیکسٹائل مصنوعات، کو ٹیرف میں چھوٹ اور کمی ملتی رہی ہے۔ اس رعایت کے بدلے پاکستان نے انسانی حقوق، مزدوروں کے حقوق اور گورننس میں بہتری جیسے وعدے کیے تھے۔پاکستان کی نازک معاشی صورتحال اور برآمدات پر انحصار کو دیکھتے ہوئے، توقع کی جا رہی تھی کہ حکومت اس قیمتی تجارتی معاہدے کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ مگر اس کے برعکس، یورپی یونین کے انسانی حقوق کے نمائندے اولوف سکوگ کے دورۂ پاکستان کے دوران ہی الیکٹرانک جرائم سے متعلق پیکا قانون میں ایسے ترمیمات کر دی گئیں جنہیں انسانی حقوق کے کارکن آزادیٔ اظہار کے مزید محدود ہونے کے مترادف سمجھتے ہیں۔ یہ صورتحال اتنی تشویشناک ہے کہ مسٹر سکوگ کو کھل کر کہنا پڑا کہ پاکستان جی ایس پی-پلس کے اسٹیٹس کو یقینی سمجھنے کی غلطی نہ کرے۔ گزشتہ سال، حکومت نے اپوزیشن پر الزام لگایا تھا کہ وہ یورپی یونین میں پاکستان کے خلاف لابنگ کر رہی ہے تاکہ یہ اسٹیٹس ختم ہو جائے۔ لیکن اس سال، خود حکومت کی پالیسیاں پاکستان کی تجارتی پوزیشن کو کمزور کر رہی ہیں۔یورپی یونین کے نمائندے نے اپنے خدشات اعلیٰ حکومتی اور عسکری قیادت تک پہنچا دیے ہیں، جن میں چیف جسٹس، آرمی چیف، وزیر قانون، وزیر تجارت، اور نائب وزیر اعظم شامل ہیں۔ امید ہے کہ ان تحفظات کو وہ سنجیدگی دی گئی ہوگی جس کی وہ متقاضی ہیں۔پاکستان کیسے چلایا جاتا ہے، یہ زیادہ تر ایک داخلی معاملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جب بین الاقوامی تجارتی معاہدوں کی پاسداری کی بات آتی ہے، تو پاکستان یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ عالمی وعدوں کی خلاف ورزی کر کے بھی مراعات سے لطف اندوز ہوتا رہے گا۔ جو لوگ اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں، انہیں اپنے اقدامات کے نتائج پر غور کرنا ہوگا، ورنہ ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔یہ محض یورپی یونین کا ایک انتباہ نہیں بلکہ پاکستان کے لیے ایک سنگین وارننگ ہے۔ اگر جی ایس پی-پلس کا درجہ ختم ہو جاتا ہے، تو یہ ملکی معیشت کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ ہماری برآمدات کا ایک بڑا حصہ یورپی منڈیوں پر انحصار کرتا ہے، اور یہ رعایت ختم ہونے کا مطلب ہوگا کہ پاکستانی مصنوعات زیادہ مہنگی ہو جائیں گی، جس کے نتیجے میں ہماری برآمدات کم ہوں گی اور بے روزگاری میں مزید اضافہ ہوگا۔حیرت کی بات یہ ہے کہ جب ملک سنگین معاشی بحران کا شکار ہے، غیر ملکی قرضوں کا بوجھ مسلسل بڑھ رہا ہے، اور عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، تو حکومت ایسے اقدامات کر رہی ہے جو معیشت کے لیے زہرِ قاتل ثابت ہو سکتے ہیں۔ کیا پالیسی سازوں کو اس حقیقت کا اندازہ نہیں کہ بین الاقوامی تجارتی معاہدے صرف کاغذی وعدے نہیں ہوتے، بلکہ ان پر عملدرآمد بھی ضروری ہوتا ہے؟یہاں یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ آزادیٔ اظہار اور معیشت کے درمیان براہِ راست تعلق موجود ہے۔ کسی بھی ملک میں کاروبار اور سرمایہ کاری اس وقت ترقی کرتی ہے جب وہاں شفافیت، اچھی حکمرانی اور آزاد عدلیہ موجود ہو۔ اگر حکومت مسلسل اظہارِ رائے پر قدغنیں لگا رہی ہے، عدلیہ کو دباؤ میں لا رہی ہے، اور اختلافِ رائے کو دبانے کی پالیسی اپنا رہی ہے، تو یہ عالمی برادری کو ایک واضح پیغام دے رہی ہے کہ پاکستان میں کاروباری ماحول مستحکم نہیں۔یورپی یونین جیسے شراکت دار انسانی حقوق کی پاسداری کو تجارتی معاہدوں کا لازمی جزو سمجھتے ہیں۔ جب پاکستان میں میڈیا پر سنسرشپ بڑھتی ہے، ڈیجیٹل معیشت کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور عدلیہ کو کمزور کیا جاتا ہے، تو عالمی برادری کے لیے یہ سب محض داخلی معاملات نہیں رہتے، بلکہ ان کی بنیاد پر وہ پاکستان کے ساتھ اپنے اقتصادی تعلقات پر نظرثانی کرتے ہیں۔یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ آیا پاکستان کے پالیسی ساز ان تباہ کن فیصلوں سے سبق سیکھیں گے یا نہیں۔ ماضی کی روشنی میں دیکھیں تو امید کم ہی ہے۔ جو پالیسیاں پچھلے تین سال میں نافذ کی گئیں، وہ نہ صرف معیشت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئیں بلکہ عوام کے بنیادی حقوق کو بھی محدود کر دیا گیا۔لیکن اب بھی وقت ہے۔ پاکستان کو اپنی پالیسیوں پر فوری نظرثانی کرنی چاہیے، آزادیٔ اظہار پر قدغنوں کو ختم کرنا چاہیے، عدلیہ کی خودمختاری کو یقینی بنانا چاہیے، اور انسانی حقوق کے حوالے سے اپنی عالمی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ صرف یورپی یونین کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ خود پاکستان کے طویل مدتی مفادات کے لیے ضروری ہے۔اگر ہم نے اپنی سمت درست نہ کی، تو شاید آنے والے وقت میں ہمیں مزید سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے۔ اس وقت فیصلہ پالیسی سازوں کے ہاتھ میں ہے: کیا وہ ملک کو ایک بہتر مستقبل کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، یا اسے مزید عدم استحکام کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں؟
خارجہ پالیسی کا جائزہ
پاکستان کی خارجہ پالیسی کو تشکیل دیے ہوئے دو دہائیاں گزر چکی ہیں، اور اب وقت آ چکا ہے کہ اس کا جامع جائزہ لیا جائے۔ سابق سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے پاکستان بزنس کونسل کے زیر اہتمام ’معاشی مکالمہ‘ کے افتتاحی سیشن میں خطاب کرتے ہوئے اسی اہم نکتے کی جانب توجہ دلائی۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ ایک مستحکم خارجہ پالیسی کی بنیاد ایک مضبوط معیشت پر ہوتی ہے، لیکن پاکستان کی کمزور معیشت، بیرونی مالی وسائل پر انحصار اور داخلی سیاسی عدم استحکام نے سفارتی محاذ پر ملک کی پوزیشن کو کمزور کر دیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا بطور ایک درمیانی طاقت ابھرنا دشوار ہو چکا ہے۔یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ گزشتہ چار سے پانچ دہائیوں کی معاشی بدنظمی اور ناقص پالیسیوں نے پاکستان کو اس نہج پر پہنچایا ہے۔ ملک کا مالیاتی ڈھانچہ بنیادی طور پر غلط بنیادوں پر کھڑا ہے، جہاں 75 سے 80 فیصد ٹیکس بالواسطہ ذرائع سے وصول کیا جاتا ہے، جس کا بوجھ امیر طبقے کے بجائے غریب عوام پر زیادہ پڑتا ہے۔ اس کے نتیجے میں غربت کی شرح 41 فیصد تک جا پہنچی ہے۔ مزید برآں، ریاستی اخراجات کو قابو میں رکھنے کے بجائے، اشرافیہ کے مالی مراعات میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو مہنگائی کی شرح سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے۔ اس کا نتیجہ مستقل بجٹ خسارے کی صورت میں نکلتا ہے، جسے پورا کرنے کے لیے پاکستان مزید اندرونی اور بیرونی قرضوں کے دلدل میں پھنستا جا رہا ہے۔یہ معاشی بدانتظامی بدعنوانی، اقربا پروری اور نااہلی سے مزید پیچیدہ ہو چکی ہے، خاص طور پر توانائی اور محصولات کے شعبے اس کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ عالمی مالیاتی ادارے اور امدادی شراکت دار ان شعبوں میں اصلاحات کا مطالبہ کرتے رہے ہیں، لیکن عملی طور پر کوئی نمایاں بہتری نظر نہیں آ رہی۔پاکستان کی معیشت صرف داخلی بدانتظامی کا شکار نہیں بلکہ یہ عالمی مالیاتی اداروں اور دوطرفہ شراکت داروں کے ساتھ تعلقات میں بھی پیچیدگی کا شکار ہو چکی ہے۔ ہر کچھ سال بعد پاکستان ایک معاشی بحران میں پھنستا ہے اور اسے بین الاقوامی مالیاتی ادارے کے پاس جانا پڑتا ہے، جس کی شرائط وقت کے ساتھ ساتھ سخت ہوتی جا رہی ہیں۔2019 سے پاکستان کو ایک منفرد صورتحال کا سامنا ہے: چین، سعودی عرب، اور متحدہ عرب امارات جیسے قریبی شراکت دار ماضی کی طرح صرف وعدوں پر یقین کرنے کے بجائے اصلاحات کے عملی نفاذ پر زور دے رہے ہیں۔ ان ممالک نے مالی امداد کو براہِ راست بین الاقوامی مالیاتی ادارے کے پروگرام کے ساتھ جوڑ دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے لیے مالیاتی آزادی مزید کم ہو گئی ہے۔یہی وہ پس منظر ہے جس میں ڈاکٹر ملیحہ لودھی کی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب معیشت کمزور ہو، ریاست قرضوں پر چل رہی ہو، اور داخلی استحکام کا فقدان ہو، تو خارجہ پالیسی خودمختار نہیں رہ سکتی۔ آج پاکستان کو اپنی بقا کے لیے بین الاقوامی مالیاتی ادارے کے پروگرام کے تحت سخت شرائط پر قرضے لینا پڑ رہے ہیں، جس کا اثر اس کی عالمی حیثیت اور سفارتی لچک پر پڑ رہا ہے۔پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ازسرِ نو جائزہ لیتے ہوئے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عالمی سطح پر بھی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ گزشتہ چند دہائیوں تک دنیا ایک یک قطبی نظام کے تحت چل رہی تھی، جہاں امریکہ عالمی امور پر حاوی تھا، لیکن اب صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ چین، جس کی معیشت 17 کھرب ڈالر کی ہو چکی ہے، تیز رفتار ترقی کی وجہ سے جلد ہی 23 کھرب ڈالر کی امریکی معیشت کے برابر آ سکتا ہے۔ مصنوعی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی میں چین کی ترقی، اور روس کی دفاعی برتری، مغربی ممالک کے لیے چیلنج بنتی جا رہی ہے۔اسی دوران، عالمگیریت بھی اپنی گرفت کھو رہی ہے۔ ماضی میں تجارتی آزادی کا جو نعرہ لگایا جاتا تھا، وہ اب امریکہ اور یورپی ممالک کے سخت تجارتی ضوابط، اقتصادی پابندیوں اور محصولات کے باعث دم توڑ رہا ہے۔ یہ صورتحال پاکستان کے لیے ایک نیا چیلنج پیدا کر رہی ہے۔ ہمارے معاشی اہداف خواہ کچھ بھی ہوں، حقیقت یہ ہے کہ ہماری دوطرفہ شراکت داریاں اب بین الاقوامی مالیاتی ادارے کے پروگرام سے مشروط ہو چکی ہیں۔ مزید برآں، مغربی ممالک کے زیرِ اثر عالمی مالیاتی ادارے جیسے عالمی بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک بھی پاکستان کے لیے سخت شرائط مقرر کر رہے ہیں۔پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل میں دو بڑے عوامل اہم کردار ادا کرتے ہیں: معاشی مجبوریوں اور سیکیورٹی خدشات۔ حالیہ عرصے میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافے نے سیکیورٹی صورتحال کو مزید نازک بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بین الاقوامی شراکت دار پاکستان کے اندرونی استحکام کے بارے میں متفکر نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غیر ملکی وفود، بشمول یورپی اتحاد اور امریکہ، اب صرف سیاسی قیادت سے ملاقات پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ عسکری قیادت سے بھی براہِ راست بات چیت کرتے ہیں۔یہ صورتحال واضح کرتی ہے کہ پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں کوئی بھی فیصلہ عجلت میں نہیں لینا چاہیے۔ ہمیں ایسے وقتی اور سطحی اقدامات سے گریز کرنا ہوگا جو مختصر مدتی فوائد تو فراہم کریں، لیکن طویل مدتی نقصان کا باعث بنیں۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی کی رائے میں، پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی کے لیے ایک جامع نظرثانی کرنی چاہیے، جس میں تمام متعلقہ فریقین کی شمولیت ہو۔ سول قیادت کو عالمی نظام میں ہونے والی تبدیلیوں اور معاشی تقاضوں کو مدنظر رکھنا ہوگا، جبکہ عسکری قیادت کو قومی سلامتی کے حقائق کی روشنی میں عملی بصیرت فراہم کرنی ہوگی۔پاکستان کے لیے یہ ایک نازک موڑ ہے، جہاں سفارتی اور معاشی بحران آپس میں گُھل مل چکے ہیں۔ اب یہ ضروری ہو چکا ہے کہ ملک اپنی خارجہ پالیسی کو نئی جہت دے، جس کی بنیاد حقیقت پسندی، معاشی خود انحصاری، اور عالمی برادری کے ساتھ بامقصد تعلقات پر ہو۔ اس وقت پاکستان کے پاس دو راستے ہیں: یا تو وہ اسی غیر مستحکم خارجہ پالیسی پر چلتا رہے، جہاں داخلی انتشار اور مالی محتاجی سفارتی اہداف کو کمزور کرتے رہیں، یا پھر ایک جامع اور مدبرانہ حکمت عملی ترتیب دے، جو ملک کو ایک مضبوط سفارتی اور اقتصادی مقام پر کھڑا کر سکے۔ فیصلہ اب پالیسی سازوں کے ہاتھ میں ہے۔ کیا وہ پاکستان کو عالمی سطح پر ایک باوقار اور خودمختار ملک کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، یا اسے مزید مالیاتی جکڑ بندیوں میں دھکیلنا چاہتے ہیں؟ اگر درست اقدامات نہ کیے گئے، تو شاید مستقبل میں ہمارے پاس کوئی مؤثر خارجہ پالیسی بنانے کا موقع ہی نہ بچے۔