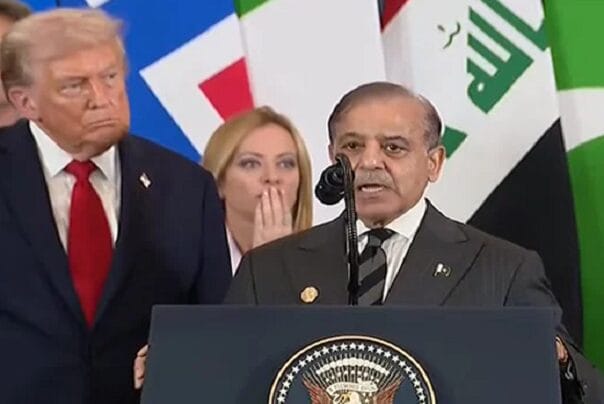تقسیمِ ہند کا المیہ ایک ایسا ناسور ہے جو وقت گزرنے کے باوجود بھی ہنوز رس رہا ہے۔ 1947 کی وہ راتیں اور دن، جب برصغیر کا نقشہ ایک نئی لکیر سے بدل دیا گیا، لاکھوں خاندانوں کی تقدیر بھی اسی لکیر کے ساتھ ہمیشہ کے لیے تقسیم ہو گئی۔ تاریخ کے صفحات پر تحریر ہونے والے ان واقعات کو ہم چاہے کتنا ہی دُہرا لیں، لیکن ان زخموں کی گہرائی کو وہی محسوس کر سکتے ہیں جو اس ہجرت کے کرب سے گزرے۔تقسیم کی کہانی صرف سیاسی معاہدوں، سرحدی حد بندیوں، اور حکمرانوں کے فیصلوں کی نہیں، بلکہ ان لاکھوں بے بس انسانوں کی بھی ہے جو ایک نئی سرحد کے ادراک سے ناواقف تھے۔ وہ جو اپنے گھروں سے نکلے، کچھ بہتر مستقبل کی امید لیے، اور کچھ محض اس خوف سے کہ ان کا ماضی اب ان کے لیے محفوظ نہیں رہا۔ ان میں وہ یتیم بچے بھی شامل تھے جن کے ماں باپ فسادات میں مارے گئے، وہ بیٹیاں جو اغوا ہوئیں، وہ عورتیں جو بے حرمتی کا شکار ہوئیں، اور وہ خاندان جو ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے۔حال ہی میں لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز – لمز میں “بوہے کھلے رکھیں” نامی ایک دستاویزی فلم کی نمائش ہوئی، جو ندا محبوب کی ہدایت کاری میں بنی اور مورخین علی عثمان قاسمی، الیاس چٹھہ، اور علی رضا نے پروڈیوس کی۔ اس فلم میں خاص طور پر ان بچوں کی کہانیوں کو اجاگر کیا گیا ہے جو فسادات میں اپنے خاندانوں سے بچھڑ گئے اور بعد میں صرف ان کے مذہب کی بنیاد پر پاکستان بھیج دیے گئے۔ یہ بچے نہ صرف اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور آبائی گھروں سے جدا ہوئے بلکہ ایک ایسے مستقبل کی طرف دھکیل دیے گئے جہاں ان کی شناخت ہمیشہ سوالیہ نشان بنی رہی۔ تقسیم کے زخموں کو بھرنے کے لیے نہ تو ریاست نے کوئی خاص کوشش کی اور نہ ہی وقت نے۔ تاہم، کچھ افراد نے ان بچھڑے ہوئے خاندانوں کو ملانے کا بیڑا اٹھایا۔ انہی میں سے ایک نام خیام چوہان کا ہے، جو دیسی انفو ٹینر”” نامی یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں۔ ان کے چینل کا مقصد وہی ہے جو ایک مورخ کا ہونا چاہیے – یعنی حقیقت کو بغیر کسی تعصب کے سامنے لانا۔ وہ تقسیم کے وقت بچھڑنے والے خاندانوں کو تلاش کرنے اور ان کی داستانیں دنیا کے سامنے پیش کرنے کا کام کر رہے ہیں۔کئی دہائیوں بعد، جب ماضی کی تلخ یادیں صرف کتابوں اور سرکاری بیانات تک محدود ہو چکی تھیں، خیام چوہان جیسے لوگ سوشل میڈیا پر ان حقیقی کہانیوں کو اجاگر کر رہے ہیں جو تاریخ کی روایتی کتابوں میں دب گئی تھیں۔ اس چینل کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے کمنٹس سیکشن میں لوگ اپنے گمشدہ رشتہ داروں کو تلاش کرتے ہیں، اپنی پہچان کے گمشدہ ٹکڑے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے جذباتی ملاپ بھی ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔یہ ایک اہم سوال ہے کہ کیا سات دہائیاں گزرنے کے بعد بھی تقسیم کے زخموں کو ہرا کرنا ضروری ہے؟ کیا یہ بار بار کی جانے والی یاد دہانی صرف بے مقصد نوحہ خوانی ہے یا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے؟حقیقت یہ ہے کہ ان کہانیوں کو محفوظ کرنا اور دنیا کے سامنے لانا نہ صرف ضروری ہے بلکہ ایک تاریخی قرض بھی ہے۔ لاکھوں لوگ جنہوں نے اپنا سب کچھ کھو دیا، ان کے تجربات کو محض ایک “سیاسی فیصلے کا نتیجہ” کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہم ان کہانیوں کو سن کر شاید تاریخ کو نہیں بدل سکتے، لیکن کم از کم اس سے سیکھ ضرور سکتے ہیں۔یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی مذہب، قومیت، اور سیاست کے نام پر نفرت کو ہوا دی گئی، اس کا نتیجہ ہمیشہ بربادی کی صورت میں نکلا۔ تقسیم کے وقت کا وہ خونی منظر نامہ آج بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ مذہبی اور قومی تعصبات جب بے قابو ہو جائیں تو وہ انسانی رشتوں کو روند کر رکھ دیتے ہیں۔ یہی سبق ہمیں آج بھی درکار ہے، خاص طور پر اس وقت جب بھارت میں مودی سرکار کی ہندوتوا پالیسی مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔بھارت میں بی جے پی (بھارتیہ جنتا پارٹی) کی قیادت میں نریندر مودی کی حکومت ایک بار پھر تقسیم کی یادوں کو زندہ کر رہی ہے۔ ہندوتوا نظریہ، جس کی جڑیں شدید مسلم دشمنی اور اقلیتوں کے استحصال میں پیوست ہیں، آج بھارت میں ایک خطرناک شکل اختیار کر چکا ہے۔ شہریت ترمیمی قانون (CAA)، رام مندر کی تعمیر، کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ، اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانات یہ سب اس بات کی علامت ہیں کہ ماضی کے زخموں کو پھر سے کریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔یہ وہی ذہنیت ہے جس نے 1947 میں لاکھوں لوگوں کو بے گھر کیا تھا، اور آج بھی یہی نظریہ بھارت میں مسلم کمیونٹی کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کی مہم چلا رہا ہے۔ اگر مسلمانوں کو حب الوطنی کے ثبوت دینے پر مجبور کیا جائے گا، اگر ان کی عبادت گاہیں مسمار کی جائیں گی، اگر انہیں مذہب کی بنیاد پر نشانہ بنایا جائے گا، تو یہ سب اسی تقسیم کی بازگشت ہے جس نے برصغیر کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔خیام چوہان کا ایک اہم شکوہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا بہت دیر سے آیا۔ وہ لوگ جو تقسیم کے اصل عینی شاہد تھے، اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ جو کچھ وہ جانتے تھے، جو درد وہ محسوس کرتے تھے، وہ سب ان کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ اگر یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہلے آ جاتے، تو شاید ہم مزید کہانیاں سن سکتے، مزید رشتے جوڑ سکتے، اور مزید حقیقتیں سامنے لا سکتے۔تاہم، دیر سے آنے کے باوجود، یہ کاوشیں رائیگاں نہیں جاتیں۔ آج بھی کچھ ایسے بوڑھے افراد موجود ہیں جو اپنی کہانیاں سنانے کے لیے بے تاب ہیں، جو اپنے بچھڑے ہوئے بہن بھائیوں کو تلاش کرنے کی آخری امید سوشل میڈیا پر لگائے بیٹھے ہیں۔تقسیم کے زخم صرف تاریخی واقعات نہیں بلکہ ایک سبق بھی ہیں۔ اگر ہم نے ان سے سبق نہ سیکھا تو تاریخ شاید دوبارہ خود کو دہرا دے۔ پاکستان اور بھارت، دونوں ممالک میں آج بھی نفرت کا کاروبار چمک رہا ہے، آج بھی مذہب اور قومیت کے نام پر سیاست کی جا رہی ہے، آج بھی ایسی سرحدی لکیر کھینچنے کی کوشش ہو رہی ہے جو دلوں کو مزید تقسیم کر دے۔لیکن شاید ہم اب بھی کچھ بدل سکتے ہیں۔ شاید ہم نفرت کی اس وراثت کو چھوڑ کر محبت اور بھائی چارے کی نئی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ شاید ہم اپنے بزرگوں کی کہانیاں سن کر سمجھ سکیں کہ انسانیت ہمیشہ سیاست اور طاقت کے کھیل سے بڑی ہوتی ہے۔ شاید یہی تقسیم کے زخموں کا وہ مرہم ہو جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔
کھویا ہوا ورثہ
پاکستان کی سرزمین، ہندوکش کے پہاڑوں سے لے کر دریائے سندھ کے کناروں اور اس کے ڈیلٹا تک، ایک عظیم ورثے کی گواہ ہے۔ یہ ورثہ ہماری شناخت کی گہرائی اور تنوع کو ظاہر کرتا ہے، مگر افسوس کہ ایک شاندار تہذیب جو صدیوں پر محیط ہے، آج زوال کا شکار ہے۔ نہ تو یہ ریاست کی ترجیحات میں شامل رہا اور نہ ہی اس کی حفاظت کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے گئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ کے بے شمار نشانات مٹ رہے ہیں، اور جو باقی بچے ہیں، وہ وقت اور بے حسی کی دھول میں دب رہے ہیں۔حال ہی میں کراچی کے ٹی ڈی ایف میگنی فائی سائنس سینٹر میں ایک منفرد ڈیجیٹل نمائش منعقد ہوئی، جس میں دریائے سندھ کے ڈیلٹا کے ثقافتی آثار کو ورچوئل سفر کے ذریعے اجاگر کیا گیا۔ یہ ڈیجیٹل ہیریٹیج ٹریل کا ایک حصہ تھا، جو میری ٹائم ای اے نامی ادارے کا منصوبہ ہے۔ یہ ادارہ ثقافتی ورثے کے تحفظ، سمندری آثارِ قدیمہ اور بلیو اکانومی کے فروغ پر کام کر رہا ہے۔ دی لاسٹ سٹیز آف دی انڈس ڈیلٹا کے تحت تاریخی مقامات جیسے کہ لہری بندر، بھمبور، راتو کوٹ قلعہ، رانو کوٹ اور جام جسکت گوٹھ کو ڈیجیٹل طور پر محفوظ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک حوصلہ افزا کوشش ہے، جو اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے کہ تاریخی ورثے کا تحفظ نہ صرف ہماری شناخت کو محفوظ رکھ سکتا ہے بلکہ معیشت کو بھی سہارا دے سکتا ہے۔ لیکن اصل چیلنج یہ ہے کہ زمینی حقائق میں تبدیلی کیسے لائی جائے، تاکہ ماحولیاتی تباہی، انسانی مداخلت اور غیر قانونی قبضے روکے جا سکیں۔یہ حقیقت کسی سے پوشیدہ نہیں کہ پاکستان میں تاریخی ورثہ بے اعتنائی، بدانتظامی اور لالچ کی بھینٹ چڑھ چکا ہے۔ آثارِ قدیمہ کے کئی اہم مقامات یا تو معدوم ہو چکے ہیں یا پھر شدید خطرے میں ہیں۔ سندھ کے علاقے میں واقع منصورہ کے آثار، جو آٹھویں صدی کی ایک شاندار بستی برہمن آباد کے کھنڈرات پر مشتمل ہیں، اس زبوں حالی کی ایک نمایاں مثال ہیں۔ یہ شہر اسلامی تہذیب کے اولین مراکز میں شمار ہوتا تھا، مگر آج یہ لاوارث پڑا ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے کوئی باڑ موجود نہیں، نہ ہی کوئی سیکیورٹی کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس بے بسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آثارِ قدیمہ کی چوری عام ہو چکی ہے، جبکہ قدرتی عوامل بھی اس کی باقیات کو ختم کر رہے ہیں۔یہ المیہ صرف منصورہ تک محدود نہیں۔ پورے ملک میں درجنوں تاریخی اور ثقافتی مقامات لاپروائی کی نظر ہو چکے ہیں۔ صدیوں پرانی عمارتیں اور قلعے وقت کے ہاتھوں زنگ آلود ہو چکے ہیں، کئی مقدس مقامات اور آثار ناجائز تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کی نذر ہو رہے ہیں۔ حکومت کی بے حسی نے ان تاریخی خزانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جہاں ثقافتی ورثے کا تحفظ دنیا کو بدل نہیں سکتا، وہاں یہ دنیا کو جینے کے قابل ضرور بنا سکتا ہے۔ کوئی بھی قوم اپنی تاریخ اور شناخت کو نظرانداز کرکے ترقی نہیں کر سکتی۔ ثقافت اور تاریخ صرف ماضی کی یادگاریں نہیں بلکہ یہ ایک قوم کی اجتماعی یادداشت ہوتی ہیں، جو اس کے مستقبل کی راہ متعین کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک اپنی تاریخ کو نہ صرف محفوظ رکھتے ہیں بلکہ اسے اپنی معیشت کا ایک اہم جزو بھی بناتے ہیں۔پاکستان میں صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہاں آثارِ قدیمہ کی حفاظت کے لیے قوانین تو موجود ہیں، مگر ان پر عملدرآمد نہ ہونے کے برابر ہے۔ 1974 کا ہیریٹیج ایکٹ اور 1994 کا سندھ کلچرل ہیریٹیج پریزرویشن ایکٹ بظاہر تحفظ کی یقین دہانی کرواتے ہیں، مگر عملی طور پر ان قوانین کی حیثیت صرف کاغذی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان قوانین کو مؤثر بنایا جائے، ان پر سختی سے عمل کیا جائے اور ورثے کے تحفظ کو ایک قومی ایجنڈا بنایا جائے۔ورثے کا تحفظ صرف تاریخی عمارتوں کی دیکھ بھال تک محدود نہیں بلکہ اس سے روزگار، سیاحت اور ترقی کے کئی دروازے کھل سکتے ہیں۔ اگر حکومت سنجیدگی سے اس جانب توجہ دے تو پاکستان کا آثارِ قدیمہ اور ثقافتی ورثہ نہ صرف بین الاقوامی سیاحوں کو راغب کر سکتا ہے بلکہ مقامی معیشت کو بھی تقویت دے سکتا ہے۔ تاریخی مقامات کی بحالی اور ان کا بہتر انتظام سیاحت کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، جس سے ہزاروں لوگوں کو روزگار میسر آ سکتا ہے۔یہ سب صرف اسی صورت ممکن ہے جب عالمی سطح پر تعاون حاصل کیا جائے اور جدید طریقے اختیار کیے جائیں۔ کئی ترقی یافتہ ممالک اپنے ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے کے لیے جدید سائنسی اور تکنیکی طریقوں کو بروئے کار لا رہے ہیں۔ ڈیجیٹل آرکائیو، تھری ڈی ماڈلنگ، اور جدید تعمیراتی بحالی کے ذریعے کھنڈرات اور تاریخی عمارتوں کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان بھی اگر اس سمت میں قدم بڑھائے تو نہ صرف اپنا ورثہ بچا سکتا ہے بلکہ اسے ایک قومی اثاثہ میں بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ورثے کا تحفظ محض اینٹوں اور پتھروں کی حفاظت کا نام نہیں، بلکہ یہ شناخت، یادداشت، رواداری اور سیکھنے کے عمل کو برقرار رکھنے کا ذریعہ بھی ہے۔ بدقسمتی سے، ہماری پالیسیوں میں ثقافتی حقوق اور شمولیت کا کوئی خاص ذکر نہیں کیا جاتا، جبکہ ایک باشعور معاشرے کی تشکیل کے لیے یہ سب سے زیادہ ضروری پہلو ہیں۔ کسی بھی قوم کی ترقی صرف معیشت یا ٹیکنالوجی سے ممکن نہیں بلکہ اس کی ثقافت اور تاریخی شعور اس کے تشخص کو مستحکم کرتے ہیں۔یہ حقیقت ہے کہ ثقافتی ورثے کا تحفظ ایک مشکل کام ہے۔ یہ وسائل، منصوبہ بندی، اور سیاسی عزم کا متقاضی ہے۔ مگر مشکل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے نظرانداز کر دیا جائے۔ اگر ہم نے اپنی تاریخ کو بچانے کے لیے ابھی اقدامات نہ کیے تو شاید کچھ سالوں بعد ہمارے پاس محفوظ کرنے کے لیے کچھ باقی ہی نہ بچے۔پاکستان کے نایاب تاریخی خزانوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت عملی اقدامات کرے، بین الاقوامی تعاون کو فروغ دے، اور اپنے ورثے کو معاشی ترقی کا حصہ بنائے۔ صرف اسی صورت میں ہم اپنی آئندہ نسلوں کے لیے وہ تاریخ چھوڑ کر جا سکتے ہیں، جس پر ہمیں فخر ہو۔ ورنہ کھنڈرات تو رہ جائیں گے، مگر ان سے جڑی کہانیاں ہمیشہ کے لیے کھو جائیں گی۔
ٹیکس کا بحران
پاکستان میں ٹیکس نیٹ کو وسعت دینا ہمیشہ ایک بڑا چیلنج رہا ہے۔ ٹیکس کی شرحیں، چاہے براہ راست ہوں یا بالواسطہ، مسلسل بڑھ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود قومی معیشت میں ٹیکس وصولی کا تناسب مطلوبہ سطح تک نہیں پہنچ پا رہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ٹیکس کی شرحیں بڑھتی ہیں، ویسے ہی ٹیکس چوری کے رجحانات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو کاروبار باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ ہیں، وہ دباؤ میں آ جاتے ہیں، اور غیر رسمی معیشت مزید مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ حکومت کو اپنی حکمت عملی پر نظرثانی کرنی ہوگی، کیونکہ رسمی معیشت میں شامل کاروباروں کے لیے ٹیکس ادا کرنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ٹیکس کی شرحوں میں مزید اضافہ کیا گیا تو یہ الٹا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔سال 2024 میں محض 59 لاکھ افراد اور کاروباری اداروں نے ٹیکس ریٹرن فائل کیے، جو 2023 میں 68 لاکھ تھے، حالانکہ ملک میں تقریباً 1.5 کروڑ افراد ٹیکس ادا کرنے کے قابل ہیں۔ یعنی تقریباً ایک تہائی ممکنہ ٹیکس دہندگان نے اپنا گوشوارہ جمع ہی نہیں کرایا، اور جو فائل کر رہے ہیں، ان کی تعداد میں بھی کمی آ رہی ہے، جو بظاہر ٹیکس کی بڑھتی ہوئی شرحوں کا ردعمل ہے۔ان گوشواروں میں بھی ایک اور حیران کن حقیقت یہ ہے کہ تقریباً نصف افراد نے اپنی آمدنی کو “صفر” قرار دیا، جبکہ صرف 8,000 افراد نے 5 کروڑ روپے سے زائد آمدنی ظاہر کی۔ مزید حیرت انگیز بات یہ ہے کہ محض 4,000 افراد ایسے تھے جنہوں نے 10 کروڑ سے زیادہ آمدنی ظاہر کی، جبکہ پورے ملک میں صرف 12 افراد نے 10 ارب روپے سے زائد آمدنی رپورٹ کی۔یہ اعدادوشمار واضح طور پر اشارہ کرتے ہیں کہ ملک میں بڑی تعداد میں افراد اور کاروبار ٹیکس ادائیگی سے گریز کر رہے ہیں۔ مگر اس کے باوجود حکومت کا حل یہ رہا ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے کے بجائے ٹیکس کی شرحوں میں مزید اضافہ کر دے، جو کہ پہلے ہی دنیا کے بلند ترین نظاموں میں شامل ہو چکا ہے۔پاکستان میں کارپوریٹ ٹیکس 29 فیصد ہے، جبکہ اس کے ساتھ 10 فیصد “سپر ٹیکس” بھی عائد ہے۔ اس کے علاوہ، مختلف قسم کے دیگر ٹیکس بھی کاروباروں کو ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اگر کوئی کمپنی منافع کماتی ہے، تو اس کے شیئر ہولڈرز کو 15 فیصد ڈیویڈنڈ ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مجموعی طور پر ایک کاروبار پر 60 فیصد سے زیادہ ٹیکس عائد ہو سکتا ہے۔سروس سیکٹر اور ملازمین کے لیے بھی صورتحال کچھ زیادہ مختلف نہیں۔ اعلیٰ آمدنی والے ملازمین کو 38.5 فیصد ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے، جبکہ غیر ملازمت پیشہ افراد کے لیے یہ شرح 48 فیصد تک پہنچ جاتی ہے۔دنیا کے وہ ممالک جہاں اتنے زیادہ ٹیکس عائد کیے جاتے ہیں، وہاں عوام کو صحت، تعلیم، ماحولیات، اور سیکیورٹی جیسی بہترین سہولیات ملتی ہیں۔ مگر پاکستان میں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ یہاں ٹیکس دینے والوں کو سہولتیں تو دور کی بات، بنیادی حقوق بھی حاصل نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیکس چوری عام ہے، کیونکہ عوام کو حکومت سے کچھ ملنے کی امید ہی نہیں۔پاکستان میں مجموعی قومی پیداوار (جی ڈی پی) کے تناسب سے ٹیکس کی وصولی 13 فیصد سے بھی کم ہے، جو عالمی معیار کے مقابلے میں نہایت کم ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں یہ شرح 30 فیصد سے تجاوز کر جاتی ہے۔ جب ٹیکس گزاروں کو بدلے میں کچھ نہ ملے، تو وہ کیوں ٹیکس دیں؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب حکومت کو دینا ہوگا۔مسئلہ صرف زیادہ ٹیکس لینے تک محدود نہیں، بلکہ اس کی غیر مساوی تقسیم بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ جو افراد اور کاروبار ایمانداری سے ٹیکس دیتے ہیں، ان پر مزید بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے، ان کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہیں ہوتی۔پاکستان میں جی ایس ٹی کی شرح 18 فیصد ہے، جو کہ دنیا کے بلند ترین سطح پر ہے۔ اس کا براہ راست نقصان یہ ہے کہ جو کاروبار ایمانداری سے ٹیکس دیتے ہیں، وہ مسابقت میں پیچھے رہ جاتے ہیں، جبکہ ٹیکس چور غیر قانونی طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ایسا نظام کاروباری ترقی کو بھی محدود کر دیتا ہے۔ جو کاروبار ایک مخصوص حد سے زیادہ بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں ٹیکس اور دیگر قانونی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں زیادہ تر کاروبار چھوٹے پیمانے پر ہی رہ جاتے ہیں اور بین الاقوامی سطح پر مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔اس کے علاوہ، وہ دولت جو ٹیکس بچانے کے لیے چھپائی جاتی ہے، وہ پیداواری شعبوں میں استعمال ہونے کے بجائے غیر پیداواری سرمایہ کاری، جیسے کہ رئیل اسٹیٹ، غیر ملکی کرنسی، اور سونے میں لگا دی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی دولت بیرون ملک منتقل کر کے دبئی اور دیگر ممالک میں جائیدادیں خرید لیتے ہیں۔ اس کا براہ راست نقصان یہ ہوتا ہے کہ مقامی صنعتوں اور سرمایہ کاری کے مواقع محدود ہو جاتے ہیں، اور ملکی معیشت ترقی نہیں کر پاتی۔ان تمام عوامل کے نتیجے میں ملک میں سرمایہ کاری کا بحران پیدا ہو چکا ہے۔ گزشتہ ایک دہائی میں نجی شعبے کی طرف سے کوئی بڑا صنعتی منصوبہ شروع نہیں کیا گیا۔ سرمایہ کاروں کے لیے حالات اس قدر غیر یقینی ہو چکے ہیں کہ پاکستان کا سرمایہ کاری سے جی ڈی پی کا تناسب پچھلے پچاس سال کی کم ترین سطح پر آ چکا ہے۔جو لوگ پاکستان میں دولت کماتے ہیں، وہ بھی شدید نقصان میں ہیں، کیونکہ روپے کی قدر میں مستقل کمی کے باعث ان کی دولت کم ہوتی جا رہی ہے۔ بلند شرح سود کی وجہ سے سرمایہ کار سرمایہ لگانے کے بجائے اپنے اثاثے بچانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔یہی صورتحال ملک کے پیشہ ور افراد کے ساتھ بھی ہو رہی ہے۔ وہ ملازمین جو 40 سے 50 فیصد تک ٹیکس ادا کر رہے ہیں، وہ مشرق وسطیٰ اور دیگر ممالک کا رخ کر رہے ہیں، جہاں انہیں ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑتا اور بہتر مواقع دستیاب ہیں۔ نتیجتاً، مالی وسائل کے ساتھ ساتھ انسانی وسائل بھی ملک سے باہر جا رہے ہیں، جو کہ کسی بھی معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔حکومت کو بھی اس بحران کا ادراک ہے۔ وزیر خزانہ تسلیم کرتے ہیں کہ ٹیکس کی شرحیں غیر متناسب ہیں، اور وہ اسے آسان بنانے کے خواہشمند ہیں۔ مگر عملی طور پر وہ ٹیکس کی شرحوں میں کمی کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں۔دوسری طرف، فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) نے ٹیکس وصولی بڑھانے کے لیے “نااہل افراد” کی ایک نئی کیٹیگری متعارف کروائی ہے، جنہیں مخصوص کاروباری لین دین یا جائیداد کی ملکیت سے روکا جائے گا۔ لیکن یہ طریقہ کار ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے کے بجائے مزید مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ایف بی آر پہلے ہی موجودہ ٹیکس دہندگان کو غیر ضروری نوٹس بھیج کر ہراساں کر رہا ہے۔ ملازمین کو ایسی شکایات ہیں کہ ان کے ادارے پہلے ہی ٹیکس کاٹ چکے ہوتے ہیں، مگر پھر بھی انہیں رسیدیں فراہم کرنے کے نوٹس موصول ہو رہے ہیں۔ اگر یہ ہراسانی نہیں تو اور کیا ہے؟دوسری طرف، حکومت عالمی مالیاتی ادارے کے دباؤ میں ہے، جس کے باعث ٹیکس اہداف پورے کرنے کے لیے مزید سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پچھلے بجٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ریٹیلرز اور رئیل اسٹیٹ ڈویلپرز کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا، لیکن اس میں بھی کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی۔ نتیجتاً، ٹیکس کا بوجھ انہی افراد پر آ رہا ہے جو پہلے ہی ادا کر رہے ہیں، اور معیشت کا رسمی شعبہ سکڑتا جا رہا ہے۔اگر حکومت نے اس مسئلے کو فوری طور پر حل نہ کیا، تو نہ صرف کاروباری طبقہ متاثر ہوگا، بلکہ ملکی معیشت مزید زوال پذیر ہو جائے گی۔