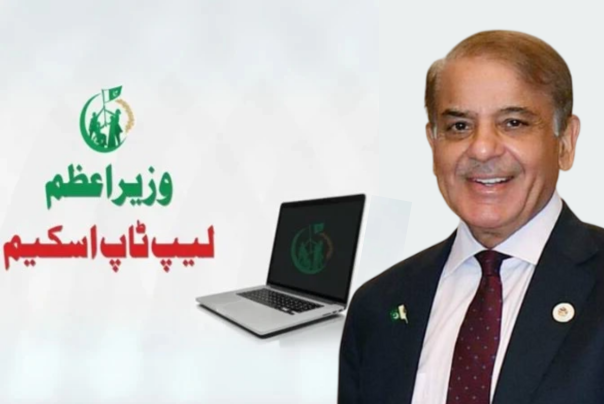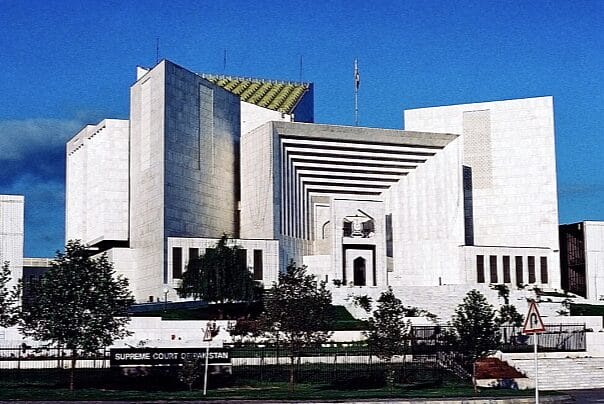پاکستان ایک بار پھر دہشت گردی اور انتہاپسندی کی نئی لہر کا سامنا کر رہا ہے، اور اس خطرناک منظرنامے میں سب سے زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس نازک موقع پر بھی ہماری قومی قیادت کی سنجیدگی، یکسوئی اور قومی وحدت کا فقدان نمایاں ہے۔ جس وقت ریاست کو اپنی ساری توانائیاں ایک اجتماعی دفاعی حکمت عملی کی تشکیل میں صرف کرنی چاہیے تھیں، ہماری قیادت ایک دوسرے پر الزام تراشی میں مصروف ہے۔ وفاقی نمائندے خیبر پختونخوا کی سیاسی قیادت کو قومی سلامتی کے بگاڑ کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، جب کہ صوبائی قیادت اور اسے چلانے والی جماعت نہ صرف وفاق کی انسدادِ دہشت گردی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے بلکہ ان پالیسیوں کو مکمل طور پر ناکام قرار دے کر وفاقی اداروں کی نیت اور صلاحیت پر بھی سوالات اٹھا رہی ہے۔یہ روش کسی بھی طور پاکستان جیسے دہشت گردی کا شکار ملک کے لیے موزوں نہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب قومی قیادت کو متحد ہو کر یہ سوچنا چاہیے تھا کہ کس طرح سے ملک دشمن عناصر کا صفایا کیا جائے۔ لیکن اس کے برعکس، ملک کی سب سے خطرناک اندرونی دشمنی — یعنی دہشت گردی — کو سیاسی بیانیے کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ ریاستی سطح پر اس نازک مسئلے پر سیاسی دکان چمکانا نہ صرف قوم کی قربانیوں کی توہین ہے بلکہ دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی بھی ہے۔یہ امر تسلیم شدہ ہے کہ انسدادِ دہشت گردی صرف بندوق سے نہیں لڑی جا سکتی۔ لیکن یہ حقیقت بھی انکار طلب نہیں کہ قومی یکجہتی، موثر منصوبہ بندی، اور اداروں کے درمیان ہم آہنگی کے بغیر بھی دہشت گردی کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ اگر وفاقی حکومت صرف پریس کانفرنسوں اور بیانات تک محدود رہے، اور خیبر پختونخوا کی قیادت محض تنقید برائے تنقید کو اپنا شعار بنائے رکھے، تو ان قوتوں کا راستہ کون روکے گا جو مذہب، قوم، اور ریاست کے نام پر معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہیں؟خیبر پختونخوا وہ خطہ ہے جو گزشتہ دو دہائیوں سے دہشت گردی کی بھٹی میں جھلس رہا ہے۔ یہاں کے لوگ اور سیکیورٹی ادارے ناقابلِ فراموش قربانیاں دے چکے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ برقرار ہے کہ اسی صوبے میں بارہا ایسے عناصر کو نرم گوشہ دیا گیا، جنہوں نے بعد میں ریاست ہی کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ طالبان سے مذاکرات کی ایک ناکام داستان ہمارے سامنے موجود ہے، جہاں ریاست نے بارہا امن کی خواہش میں شدت پسندوں کو رعایت دی، لیکن جواب میں خونریزی ملی۔اب ایک بار پھر اگر صوبائی حکومت اپنی پوزیشن کو سیاسی مفاد کی عینک سے دیکھے گی، اور وفاقی حکومت عوامی نمائندوں کی آواز کو نظر انداز کرے گی، تو اس کشمکش کا فائدہ صرف دہشت گرد ہی اٹھائیں گے۔ ہر روز جو پولیس اہلکار، فوجی جوان، اور معصوم شہری دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں، ان کے قاتل اس باہمی سیاست کو دیکھ کر صرف مسکرا رہے ہوں گے۔یہ بات سمجھنی ہوگی کہ دہشت گردی کوئی معمولی مسئلہ نہیں بلکہ یہ ایک قومی وجود کے لیے خطرہ ہے۔ ایسے میں وفاق اور صوبے کی قیادت کا رویہ ایک دوسرے کے مدمقابل نہیں بلکہ شانہ بشانہ ہونا چاہیے۔ قومی سلامتی کی حکمتِ عملی میں کسی ایک سیاسی جماعت یا کسی ایک ادارے کی سوچ نہیں بلکہ ایک مشترکہ قومی بیانیہ شامل ہونا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی ہم پرانے طرزِعمل کو دہرا رہے ہیں اور مختلف نتائج کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ یہی طرزِعمل ہمیں 2009، 2014 اور 2021 کی خطرناک لہروں میں دھکیل چکا ہے۔آج دہشت گردی صرف کسی پہاڑی علاقے یا سرحدی پٹی کا مسئلہ نہیں بلکہ شہری مراکز، عبادت گاہوں، تعلیمی اداروں اور بازاروں تک پھیل چکی ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں دشمن ہماری صفوں میں گھس چکا ہے، جو شناخت سے بالاتر ہو چکا ہے، جو نظریے کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے، لیکن دراصل خون اور وحشت کا علمبردار ہے۔ ایسے دشمن سے لڑنے کے لیے قیادت کو خود اپنی صفوں میں انتشار ختم کرنا ہوگا۔وفاقی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے عوام کی آواز سنے۔ اگر ان کی قیادت کسی حکمتِ عملی پر اعتراض کر رہی ہے تو اس کا مقصد انکار برائے انکار نہ ہو بلکہ اس کا حل تلاش کیا جائے۔ عوام کے ووٹ سے منتخب حکومتوں کو مکمل اعتماد دینا بھی جمہوریت کا حصہ ہے۔ اگر خیبر پختونخوا کی حکومت کسی پالیسی کو مؤثر نہیں سمجھتی، تو اسے متبادل پیش کرنا چاہیے نہ کہ صرف مخالفت۔ اس کے برعکس، وفاق کو بھی چاہیے کہ وہ صوبے کی شکایات کو سیاسی الزام نہ سمجھے بلکہ سنجیدگی سے جائزہ لے اور اس بنیاد پر پالیسیاں ترتیب دے۔دہشت گردی کے خلاف جنگ کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ یہ ایک ‘ہم سب’ کی جنگ ہے۔ اس میں نہ کوئی جماعت اکیلے فتح حاصل کر سکتی ہے، نہ کوئی ادارہ۔ یہ اتحاد، یکجہتی اور قومی وژن کی جنگ ہے۔ ایسے وقت میں جب ہم پر باہر سے بھی دباؤ ہے، اندرونی خلفشار اور الزام تراشی صرف کمزوری کا سبب بنے گییہ وقت ہے کہ تمام قومی ادارے، سیاسی جماعتیں اور قیادت ایک صف میں کھڑی ہو، اور اپنے بیانات، پالیسیوں اور اقدامات میں وہ احتیاط برتیں جس کا تقاضا ایک جنگ زدہ ریاست کرتی ہے۔ یہ وقت ہے کہ عوام کو یہ پیغام دیا جائے کہ ریاست ایک ہے، اس کے دشمن مشترک ہیں، اور ان کا مقابلہ مل کر کیا جائے گا۔دہشت گردی کو سیاسی مسئلہ بنا دینا دراصل اس جنگ کو طول دینا ہے۔ عوام اب تھک چکے ہیں۔ وہ امن چاہتے ہیں، تحفظ چاہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی قیادت سنجیدہ ہو، سنجیدہ فیصلے کرے، اور سنجیدہ اتحاد قائم رکھے۔اگر ہم نے آج بھی ہوش کے ناخن نہ لیے، تو کل شاید بہت دیر ہو چکی ہو۔ دشمن ہمارے درمیان ہے، خاموش اور خطرناک۔ اور وہ صرف ایک چیز سے ڈرتا ہے — قومی اتحاد سے۔ کیا ہم وہ اتحاد دکھانے کے لیے تیار ہیں؟ یا ہم پھر سے سیاسی بیان بازی کے میدان میں الجھ کر اپنی شکست خود لکھنے جا رہے ہیں؟ وقت اس سوال کا جواب ہم سے مانگ رہا ہے — اور بہت جلد۔
زراعت کا مالیاتی بحران
پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کہلانے والا زرعی شعبہ ایک گہرے اور پیچیدہ بحران سے دوچار ہے۔ مالیاتی وزیر محمد اورنگزیب نے حال ہی میں پارلیمنٹ میں اپنے تحریری بیان میں جو حقائق پیش کیے ہیں، وہ نہ صرف تشویشناک ہیں بلکہ اس بات کی علامت بھی ہیں کہ اگر فوری اصلاحی اقدامات نہ کیے گئے تو زراعت — جو ملکی آبادی کے 70 فیصد سے زائد افراد کے روزگار کا ذریعہ ہے — مزید زوال کا شکار ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ زرعی قرضوں میں شدید کمی اس بحران کا بنیادی سبب بن چکی ہے، جس نے کسانوں کو نقدی کی قلت میں مبتلا کر دیا ہے اور ان کی پیداواری سرگرمیوں کو بری طرح متاثر کیا ہے۔اس وقت ملک میں چھوٹے کسان سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ تازہ ترین زرعی مردم شماری کے مطابق 97 فیصد کسان ایسے ہیں جن کے پاس ساڑھے بارہ ایکڑ سے کم زمین ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زرعی بحران محض چند علاقوں یا بڑے زمینداروں کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے دیہی پاکستان میں جڑ پکڑ چکا ہے۔ چھوٹے اور بکھرے ہوئے کھیت، سرمایہ کی کمی، قرضوں تک محدود رسائی، اور غیر جدید کاشتکاری کے طریقے وہ وجوہات ہیں جنہوں نے اس شعبے کی نمو کو جکڑ رکھا ہے۔محمد اورنگزیب نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ زرعی معیشت میں نقدی کے مسائل کی بنیاد فصلوں کی ناکامی، کم پیداوار اور منڈی میں قیمتوں کے اتار چڑھاؤ میں پوشیدہ ہے۔ جب کسان اپنی فصلیں وقت پر فروخت نہیں کر پاتے یا ان کی قیمت اخراجات پورے نہیں کرتی، تو وہ قرضوں کی ادائیگی میں تاخیر کرتے ہیں۔ نتیجتاً بینک ان کے لیے قرضوں کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ — جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا زرعی قرض دہندہ ادارہ ہے — نے صرف دو سالوں میں اپنے قرضوں کی تقسیم میں 54 فیصد کمی کی۔ 2024 میں یہ رقم 85.66 ارب روپے تھی، جو 2025 میں گھٹ کر صرف 39.66 ارب روپے رہ گئی۔یہ کمی ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب زراعت کو سب سے زیادہ مالیاتی مدد درکار تھی۔ سیلاب، غیر متوقع بارشیں، درجہ حرارت میں اضافہ اور پانی کی قلت نے فصلوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ دوسری طرف بیج، کھاد، کیڑے مار ادویات اور ایندھن کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ اس صورتِ حال میں جب چھوٹا کسان قرض تک رسائی سے محروم ہو جائے تو وہ زمین چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیہی علاقوں سے شہروں کی طرف ہجرت میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے شہری بنیادی ڈھانچے پر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے۔یہ صورتحال اس لیے بھی تشویشناک ہے کہ زراعت نہ صرف دیہی معیشت بلکہ برآمدی شعبے کے لیے بھی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ کپاس، چاول، گندم، گنا، اور پھلوں کی برآمدات ملکی زرمبادلہ کا اہم ذریعہ ہیں۔ ان میں کمی کا مطلب ہے کہ پاکستان کی برآمدی آمدنی مزید کم ہو گی، جس سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ دوبارہ بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو جائے گا۔یہ درست ہے کہ کسان بھی اس زوال کے جزوی ذمہ دار ہیں۔ آج بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں پرانے اور غیر مؤثر طریقہ ہائے کاشت رائج ہیں۔ مشینری کا استعمال محدود ہے، جدید بیجوں سے گریز عام ہے، اور زرعی تحقیق کے نتائج کھیتوں تک نہیں پہنچ پاتے۔ مگر اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ جب کسان کے پاس سرمایہ ہی نہیں ہوگا تو وہ جدید آلات یا بہتر بیج خریدے گا کیسے؟ اس لیے مسئلے کی جڑ مالیاتی ڈھانچے میں ہے، جہاں کسان کو سرمایہ فراہم کرنے کا نظام منجمد ہو چکا ہے۔حکومت کے حالیہ اقدامات اگرچہ قابلِ تعریف ہیں، مگر ان کے اثرات اس وقت تک محدود رہیں گے جب تک ان پر عمل درآمد کو یقینی نہیں بنایا جاتا۔ اگست میں وفاقی حکومت نے “چھوٹے کسانوں کے لیے خطرہ کوریج اسکیم” کا آغاز کیا، جس کا مقصد بینکوں کو اس بات کی ترغیب دینا ہے کہ وہ ایسے کسانوں کو بھی قرض فراہم کریں جو پہلے اس نظام سے باہر تھے۔ اس کے بعد اسٹیٹ بینک نے “قومی اعانتِ کسان اقدام” متعارف کرایا ہے — ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے بغیر ضمانت قرضوں کی فراہمی کا نظام۔ اس اسکیم میں لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم کے تحت زمینوں کے ریکارڈ کی تصدیق کی جاتی ہے، اور پھر بینک قرض فراہم کرتا ہے، جس کا 75 فیصد حصہ سامان کی صورت میں دیا جاتا ہے تاکہ معیاری بیج، کھاد اور کیڑے مار ادویات براہ راست منظور شدہ تاجروں سے فراہم کی جائیں، جبکہ بقیہ 25 فیصد رقم نقدی کی صورت میں کسان کو ملتی ہے تاکہ وہ دیگر ضروری اخراجات پورے کر سکے۔یہ تصور بظاہر مثالی ہے، لیکن اس پر کامیاب عمل درآمد کا انحصار دو عوامل پر ہے: ایک، بینکنگ نظام کی استعداد کہ وہ ان اسکیموں کو دیہی علاقوں میں واقعی نافذ کر سکے؛ اور دوسرا، کسانوں کی ڈیجیٹل تعلیم، یعنی کیا وہ آن لائن درخواست دینے، ڈیجیٹل تصدیق کے مراحل سمجھنے، اور اپنے ریکارڈ برقرار رکھنے کے قابل ہیں؟ پاکستان کے بیشتر دیہی علاقوں میں انٹرنیٹ کی رسائی محدود ہے، اور کسانوں کی بڑی تعداد اب بھی نقد لین دین پر انحصار کرتی ہے۔ ایسے میں یہ ڈیجیٹل منصوبے اگر زمینی حقائق کے مطابق نہ ڈھالے گئے تو محض کاغذی کارروائی بن کر رہ جائیں گے۔زرعی معیشت کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ مالیاتی نظام کو عملی حقیقتوں سے ہم آہنگ کیا جائے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ بینکوں کو مراعات دے تاکہ وہ کسانوں کے لیے قرض کی فراہمی میں نرمی کریں۔ دوسری طرف، زرعی ترقیاتی بینک کو ازسرِ نو منظم کرنا ہو گا تاکہ وہ محض سرکاری بیوروکریسی کے شکنجے میں نہ رہے بلکہ ایک فعال، منافع بخش اور عوامی خدمت کے ادارے کے طور پر کام کرے۔ایک اور پہلو جو توجہ کا متقاضی ہے وہ ہے بیمہ نظام۔ فصل بیمہ کے بغیر کسان ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے۔ کسی قدرتی آفت یا منڈی میں قیمتوں کے اچانک گرنے سے وہ مالی طور پر تباہ ہو جاتا ہے۔ اگر حکومت فصل بیمہ کو قومی سطح پر مؤثر انداز میں نافذ کرے، تو کسان قرضوں کی ادائیگی میں بھی بااعتماد ہو جائے گا اور زرعی پیداوار میں استحکام پیدا ہو گا۔یہ بھی ضروری ہے کہ زرعی تحقیق اور توسیعی خدمات کو مضبوط کیا جائے۔ صوبائی زرعی محکمے اکثر محض نمائشی کردار ادا کرتے ہیں۔ نئی ٹیکنالوجی، موسمی تغیر سے ہم آہنگ فصلوں اور جدید آبپاشی کے طریقوں پر تحقیق اگر کھیت تک نہیں پہنچے گی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کسانوں کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچنے کے لیے تربیت دینا بھی لازمی ہے۔یہ امر باعثِ افسوس ہے کہ ہماری معیشت میں زراعت کو وہ ترجیح نہیں دی جاتی جو اسے حاصل ہونی چاہیے۔ بجٹ میں زرعی ترقیاتی پروگراموں کے لیے مختص رقم ہر سال کم کر دی جاتی ہے، جبکہ غیر ترقیاتی اخراجات میں اضافہ جاری رہتا ہے۔ اس کے برعکس، بھارت، بنگلہ دیش اور چین جیسے ممالک میں زرعی سبسڈی، جدید تحقیق، اور قرضوں کے سستے ذرائع نے اس شعبے کو ایک مستحکم ستون بنا دیا ہے۔پاکستان میں اگر زرعی شعبہ اس بحران سے نکلنا چاہتا ہے تو حکومت کو جامع اصلاحاتی پالیسی اپنانی ہوگی۔ زرعی قرضوں کی بحالی کے ساتھ ساتھ مارکیٹ اصلاحات بھی ناگزیر ہیں۔ منڈی کے نظام میں شفافیت لانا، کسانوں کو براہِ راست خریداروں سے جوڑنا، اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی وہ اقدامات ہیں جو فوری طور پر کسان کے معاشی حالات میں بہتری لا سکتے ہیں۔آخر میں یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ زرعی بحران محض معاشی نہیں بلکہ سماجی بحران بھی ہے۔ جب کسان زمین چھوڑ دیتا ہے تو صرف ایک فرد نہیں بلکہ ایک پوری ثقافت، دیہی زندگی کا ایک نظام اور قومی خودکفالت کا ایک خواب ماند پڑ جاتا ہے۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ زرعی قرضوں کے بحران کو قومی ترجیح کے طور پر دیکھے۔ زرعی ترقیاتی بینک اور دیگر مالیاتی ادارے اس وقت تک اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے جب تک ان کی پالیسیوں میں شفافیت، جواب دہی اور کسان دوستی شامل نہ ہو۔اگر ریاست نے بروقت اور ٹھوس فیصلے نہ کیے تو دیہی معیشت مزید سکڑ جائے گی، شہروں پر بوجھ بڑھے گا، اور ملک کی غذائی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس کے برعکس، اگر چھوٹے کسان کو سہارا دیا گیا، قرض کی راہیں کھولی گئیں، اور زرعی پیداوار کو جدید خطوط پر استوار کیا گیا تو یہی بحران پاکستان کے لیے ایک نئے زرعی انقلاب کی بنیاد بن سکتا ہے۔ زرعی معیشت کی بحالی صرف فصلوں کی بہتری نہیں، بلکہ قوم کی بقا کا سوال ہے۔
معاشی استحکام کی جھلک
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مالی سال 2025 کی سالانہ رپورٹ میں ملکی معیشت کے اہم اشاریوں میں بہتری کی واضح تصویر پیش کی گئی ہے۔ مجموعی قومی پیداوار یعنی مجموعی داخلی پیداوار کی شرح نمو مالی سال 2025 میں تین فیصد رہی جو پچھلے سال کی 2.4 فیصد کے مقابلے میں قدرے بہتری ہے، حالانکہ زراعت کے شعبے میں نمایاں گراوٹ دیکھنے میں آئی — گزشتہ برس 6.4 فیصد کی ترقی کے مقابلے میں رواں سال یہ شرح صرف 1.5 فیصد رہی۔ صنعتی شعبے میں بہتری نظر آئی، جہاں شرح نمو 5.3 فیصد رہی، جو پچھلے سال کے 0.9 فیصد کے مقابلے میں خاصی بہتری ہے، اگرچہ بڑے پیمانے پر صنعتوں نے منفی 0.7 فیصد کی کارکردگی دکھائی جو پچھلے سال کے مثبت 0.9 فیصد کے برعکس ہے۔تین فیصد کی شرح نمو اسٹیٹ بینک اور پاکستان بیورو برائے شماریات کی ابتدائی تخمینوں سے 0.4 فیصد کم رہی، تاہم تشویشناک بات یہ ہے کہ عالمی بینک نے پاکستان کی ترقی کی شرح 2.6 فیصد جبکہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے 2.7 فیصد برقرار رکھی، جس میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کی معاشی بہتری کو اب بھی غیر مستحکم اور محتاط نگاہ سے دیکھ رہے یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ملک میں شدید بارشوں اور سیلاب کا آغاز جون میں ہوا، جب کہ مالی سال کا اختتام بھی اسی مہینے ہوتا ہے، اور ممکنہ طور پر سیلاب کے اثرات کا مکمل تخمینہ نہ ہونے کے سبب حکام نے اسے اپنے تخمینوں میں شامل نہیں کیا۔ لیکن یہی غیر یقینی صورتحال شاید عالمی اداروں کی جانب سے ترقی کی شرح میں اضافے سے گریز کا سبب بنی۔رپورٹ میں بڑے پیمانے پر صنعتوں کی منفی کارکردگی کو ملکی برآمدات میں کمی کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ برآمدات کا تناسب جی ڈی پی کے حوالے سے 11.1 فیصد سے گر کر 4.3 فیصد پر آ گیا جبکہ درآمدات میں بڑے پیمانے پر کمی دیکھنے میں آئی — 2024 میں 0.9 فیصد سے کم ہوکر 11.2 فیصد پر۔ اس کمی کا نتیجہ کرنٹ اکاؤنٹ میں بہتری کی صورت میں سامنے آیا، جو 2024 میں منفی 2.072 ارب ڈالر سے بڑھ کر 2025 میں 2.113 ارب ڈالر مثبت ہو گیا۔یہ کمی اگرچہ بظاہر خوش آئند ہے، تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ درآمدات میں کمی کی بنیادی وجہ خام مال اور نیم تیار شدہ مصنوعات کی درآمد میں رکاوٹیں تھیں، جس کا اثر مقامی صنعت پر پڑا اور بڑے پیمانے کی صنعتوں کی منفی شرح نمو اسی کا عکس ہے۔رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ نجی شعبے کے قرضوں میں جی ڈی پی کے تناسب سے دوگنا اضافہ ہوا — 6.1 فیصد سے بڑھ کر 12.2 فیصد — لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ اثر صنعتی پیداوار پر نہیں پڑا۔ اس سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ یہ قرضے پیداواری سرمایہ کاری کے بجائے قیاسی یا غیر پیداواری سرگرمیوں میں استعمال کیے گئے، جو معیشت کے لیے تشویش کا باعث ہے۔جہاں تک مثبت پہلوؤں کا تعلق ہے، مہنگائی میں نمایاں کمی رپورٹ کی گئی ہے — 2024 کے 23.4 فیصد سے گر کر 2025 میں صرف 4.5 فیصد تک۔ اسی طرح شرح سود میں بھی کمی آئی ہے — 2024 میں 20.5 فیصد سے کم ہو کر 2025 میں 11 فیصد تک۔ تاہم، اس میں دو اہم نکات پر توجہ دینا ضروری ہے۔اولاً، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے جولائی 2025 سے پاکستان کو تکنیکی معاونت فراہم کرنا شروع کی ہے تاکہ جی ڈی پی کے ایک تہائی حصے پر مشتمل ڈیٹا میں موجود خامیوں کو دور کیا جا سکے۔ خاص طور پر پیداوار کی قیمتوں کے اشاریہ میں بہتری کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے، کیونکہ موجودہ ڈیٹا میں باریک بینی، قابل اعتمادیت اور معیاری تعریفوں کی کمی ہے۔