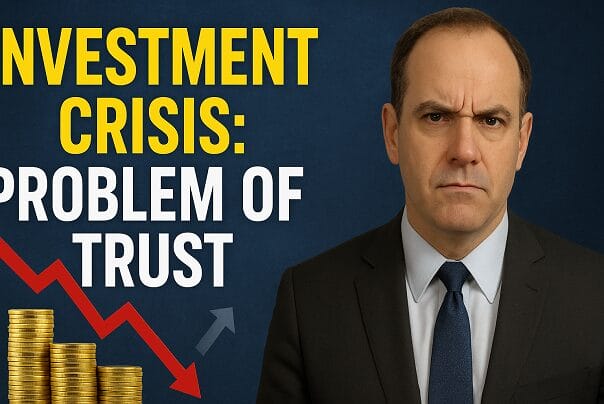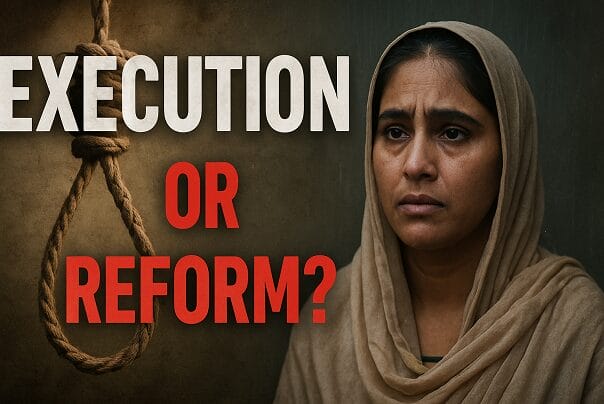بھارت اور امریکہ کے تعلقات کو طویل عرصے سے اسٹریٹجک شراکت داری کی علامت سمجھا جاتا رہا ہے۔ گزشتہ دو دہائیوں میں دونوں ممالک نے دفاع، تجارت، ٹیکنالوجی اور عالمی سفارت کاری کے میدانوں میں ایک دوسرے کے قریب آنے کی پالیسی اپنائی۔ خاص طور پر چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے امریکہ کے نزدیک بھارت ایک قدرتی اتحادی کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے۔ مگر حالیہ ہفتوں میں سامنے آنے والے واقعات نے اس تاثر کو شدید دھچکا پہنچایا ہے۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارتی مصنوعات پر 25 فیصد اضافی ٹیرف لگانے کا اعلان، اور یہ عندیہ دینا کہ کچھ اشیاء پر ڈیوٹی 50 فیصد تک بڑھ سکتی ہے، نہ صرف تجارتی تعلقات کو متاثر کرے گا بلکہ سفارتی ماحول میں بھی سرد مہری پیدا کرے گا۔ اس اقدام کی بنیادی وجہ بھارت کی جانب سے روسی تیل کی درآمدات کو جاری رکھنا بتائی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جہاں واشنگٹن اپنی جغرافیائی سیاسی ترجیحات کو دہراتا ہے، جبکہ دہلی اپنے معاشی مفادات اور توانائی کی ضروریات کو ترجیح دیتا ہے۔
صورتحال اس وقت مزید بگڑی جب رپورٹس آئیں کہ ٹرمپ نے پاکستانی فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا، اور ممکنہ طور پر بھارتی وزیرِاعظم نریندر مودی اور منیر کے درمیان ملاقات کا اہتمام کرنے کی کوشش کر سکتے تھے۔ مودی نے اس خدشے کے پیش نظر وائٹ ہاؤس کا دورہ کرنے سے انکار کیا اور یورپ کے ایک پہلے سے طے شدہ دورے کو ترجیح دی۔ دہلی کی نظر میں کسی پاکستانی فوجی سربراہ کو وائٹ ہاؤس میں سرکاری عزت دینا اس بات کا اشارہ ہے کہ واشنگٹن خطے کی فوجی سیاست میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے — جو بھارت کے لیے قابلِ قبول نہیں۔
تجارت کے محاذ پر بھی دونوں ممالک میں کئی سال سے اختلافات موجود ہیں۔ امریکہ بھارت کی وسیع زرعی اور ڈیری منڈی تک رسائی چاہتا ہے، مگر مودی حکومت کسانوں اور مقامی پیداوار کنندگان کے دباؤ میں یہ دروازے کھولنے سے گریزاں ہے۔ مودی نے حالیہ تقریر میں واضح کر دیا کہ وہ زرعی شعبے میں کسی بھی قسم کا سمجھوتہ نہیں کریں گے، چاہے اس کے لیے انہیں ذاتی سیاسی قیمت ہی کیوں نہ چکانی پڑے۔
بھارت کی سفارتی حکمتِ عملی ہمیشہ “اسٹریٹجک خودمختاری” کے اصول پر مبنی رہی ہے — یعنی بڑے طاقتور ممالک کے ساتھ تعلقات میں توازن رکھنا اور کسی ایک بلاک میں زیادہ جھکاؤ نہ رکھنا۔ مگر چین کے ساتھ 2014 کے بعد سے بڑھتے ہوئے سرحدی تنازعات اور اس کے اقتصادی دباؤ نے بھارت کو امریکہ کی طرف مزید مائل کیا۔ اس کے باوجود، موجودہ صورتِ حال نے یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ امریکہ کسی موقع پر اپنے تزویراتی مفاد کے لیے بھارت پر بھی دباؤ ڈال سکتا ہے۔
اس حالیہ کشیدگی نے دہلی میں پالیسی سازوں کو ایک بار پھر سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کیا امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات چین یا روس جیسے دیگر طاقتور ممالک سے فاصلہ رکھنے کے قابل ہیں؟ یا پھر بھارت کو پرانی حکمتِ عملی کی طرف لوٹ کر تمام بڑی طاقتوں سے مساوی فاصلے پر رہنا چاہیے؟ یہی سوال اس بحران کی جڑ ہے، اور اس کا جواب بھارت کے آئندہ برسوں کی خارجہ پالیسی کا رخ متعین کرے گا۔
بھارت اور امریکہ کے درمیان پیدا ہونے والا یہ تناؤ صرف دو ملکوں تک محدود نہیں رہے گا۔ جنوبی ایشیا ایک ایسا خطہ ہے جہاں عالمی طاقتوں کی پالیسیوں کے معمولی جھکاؤ بھی بڑے جغرافیائی اثرات پیدا کر دیتے ہیں۔ اس تازہ کشیدگی کے سب سے براہِ راست اثرات پاکستان پر مرتب ہو سکتے ہیں — اور وہ بھی کئی جہتوں سے۔
پہلی جہت سفارتی ہے۔ اگر واشنگٹن دہلی کے ساتھ فاصلہ بڑھاتا ہے تو اسے خطے میں اپنی حکمتِ عملی کے لیے متبادل پارٹنرز کی تلاش ہوگی۔ پاکستان، جو پہلے ہی امریکہ اور چین دونوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے پاکستانی فوجی قیادت کو وائٹ ہاؤس میں مدعو کرنا اس بات کا عندیہ ہے کہ واشنگٹن اسلام آباد کو نظر انداز کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس سے پاکستان کو خطے میں اپنی اسٹریٹجک اہمیت جتانے کا موقع ملتا ہے۔
دوسری جہت اقتصادی ہے۔ اگر بھارت پر امریکی ٹیرف برقرار رہتے ہیں تو کچھ شعبوں میں پیدا ہونے والے تجارتی خلا کو پاکستان جزوی طور پر پُر کر سکتا ہے۔ خاص طور پر ٹیکسٹائل اور زرعی مصنوعات کے شعبے میں پاکستان امریکی مارکیٹ میں مسابقتی حیثیت حاصل کر سکتا ہے۔ تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلام آباد اپنی پیداواری صلاحیت اور برآمدی معیار کو عالمی تقاضوں کے مطابق ڈھالے۔
تیسری جہت خطے کے تزویراتی توازن سے متعلق ہے۔ بھارت اگر امریکہ کے ساتھ سرد مہری محسوس کرے تو چین اور روس کے ساتھ اپنے روابط کو مضبوط کر سکتا ہے۔ یہ تبدیلی خطے میں طاقت کے توازن کو بدل سکتی ہے، خاص طور پر اگر چین، بھارت اور روس کے درمیان کوئی مشترکہ مفاہمت وجود میں آتی ہے۔ ایسی صورت میں پاکستان کو اپنی پالیسی میں مزید احتیاط اور دور اندیشی کی ضرورت ہوگی تاکہ وہ کسی بڑے بلاک میں ضرورت سے زیادہ جھکاؤ سے بچ سکے۔
چوتھی جہت دفاعی اور سلامتی کے پہلو سے جڑی ہے۔ اگر امریکہ بھارت پر فوجی اور انٹیلی جنس تعاون کے حوالے سے دباؤ کم کرتا ہے تو خطے میں طاقت کا توازن جزوی طور پر پاکستان کے حق میں جھک سکتا ہے۔ تاہم، بھارت اس کمی کو روس یا اسرائیل جیسے اتحادیوں سے پورا کرنے کی کوشش کرے گا، اس لیے یہ فائدہ مستقل نہیں ہوگا۔
پاکستان کے لیے اصل موقع اس بات میں ہے کہ وہ اس صورتحال کو اپنی خارجہ پالیسی میں زیادہ وسعت پیدا کرنے کے لیے استعمال کرے۔ اگر اسلام آباد واشنگٹن کے ساتھ تعلقات کو نئے سرے سے متوازن انداز میں آگے بڑھائے، بیجنگ کے ساتھ اقتصادی تعاون کو مستحکم کرے، اور خطے میں اعتماد سازی کے اقدامات کرے، تو یہ پاکستان کو ایک اہم علاقائی کھلاڑی کے طور پر مزید مستحکم کر سکتا ہے۔
تاہم خطرہ یہ بھی ہے کہ بھارت-امریکہ کشیدگی کا رخ کسی نئی بھارت-چین قربت کی طرف ہو، جو پاکستان کے لیے مخمصہ پیدا کر سکتی ہے۔ ایسی صورت میں اسلام آباد کو دو بڑے ہمسایہ ممالک کے درمیان توازن قائم رکھنے کے لیے اپنی پالیسی میں مزید لچک پیدا کرنی ہوگی۔
آخرکار، یہ بحران جنوبی ایشیا میں طاقت کی سیاست کا ایک نیا باب کھول سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں وہ اپنی سفارتی مہارت، اقتصادی اصلاحات اور دفاعی تیاریوں کو بروئے کار لا کر خطے میں اپنی پوزیشن مضبوط کر سکتا ہے — لیکن یہ سب کچھ اس شرط پر منحصر ہے کہ اسلام آباد اس وقت کو محض تماشائی کے طور پر گزارنے کے بجائے فعال کردار ادا کرے۔
سوشل میڈیا کا زہر — نفرت کے کلچر سے خود کو کیسے بچائیں
ڈیجیٹل دور نے دنیا کو بلاشبہ ایک گاؤں میں بدل دیا ہے۔ چند کلکس میں فاصلے مٹ جاتے ہیں، خیالات، خبریں اور تخلیقات سرحدوں کو عبور کر لیتی ہیں۔ مگر اسی آسانی نے ایک ایسا دروازہ بھی کھول دیا ہے جہاں نفرت، تعصب اور زہریلی سوچ بے روک ٹوک پھیلتی ہے۔ حالیہ دنوں میں ماڈل و اداکارہ صحیفہ جبار خٹک نے سوشل میڈیا پر ایک ایسے ہی رجحان کے خلاف آواز بلند کی ہے، جو بظاہر “تفریح” کے نام پر، مگر حقیقت میں معاشرتی زہر پھیلانے کے مترادف ہے۔
صحیفہ نے انسٹاگرام پر مختلف ریلز شیئر کیں جن میں نوجوان، خاص طور پر اپنی 20 اور 30 کی دہائی کے لوگ، دوسروں کو اُن کے نام، ذات، آمدنی یا دیگر ذاتی خصوصیات کی بنیاد پر “ریٹ” کرتے دکھائی دیے۔ یہ محض ایک ہلکا پھلکا کھیل نہیں بلکہ تعصب، نسلی برتری اور سماجی تقسیم کو بڑھاوا دینے والا رویہ ہے۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں لسانی اور مذہبی تناؤ پہلے ہی موجود ہو، یہ طرزِ عمل سماجی امن کے لیے خطرناک ہے۔ صحیفہ کا یہ سوال — “ہم بطور قوم کیا کر رہے ہیں؟” — محض ایک ذاتی رائے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ایک اجتماعی تنبیہ ہے۔
اداکارہ نے خاص طور پر “زہریلی مردانگی” کے فروغ پر تنقید کی، جس میں ایسے مردوں کو “ہیرو” کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو جارحانہ، متشدد یا عورتوں کے لیے خطرناک رویے رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس بدنما سوچ کو بھی چیلنج کیا جو جنسی ہراسانی کی شکار خواتین کو ہی شرمندگی کا باعث قرار دیتی ہے۔ یہ نہ صرف غیر اخلاقی بلکہ انسانی شرافت کے منافی رویہ ہے، جو مظلوم کو مزید مظلوم بنانے کے مترادف ہے۔
سوشل میڈیا کی زبان اور مکالمے کا معیار بھی تنزلی کا شکار ہے۔ گالم گلوچ، ذلیل کرنے والے جملے اور نفرت انگیز اصطلاحات عام ہو چکی ہیں۔ صحیفہ کا کہنا کہ “ان بچوں کے ہاتھ سے فون لے لو اور انہیں تعلیم دو” ایک جذباتی ردعمل ہے، مگر اس کے پیچھے ایک سچائی ہے — ہمیں اپنی نئی نسل کو صرف ٹیکنالوجی دینے کے بجائے، اس کے ذمہ دارانہ استعمال کی تربیت دینا ہوگی۔ موبائل فونز یا انٹرنیٹ مکمل طور پر چھین لینا ممکن نہیں، مگر بہتر آن لائن نگرانی، والدین کی شمولیت اور مثبت مواد کی حوصلہ افزائی کے ذریعے اس خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے۔
اداکارہ نے طبقاتی تفاوت کو ہوا دینے والے رجحانات جیسے “لباس کی قیمت بتانے” پر بھی تنقید کی۔ یہ رویہ بظاہر معصوم معلوم ہوتا ہے مگر عملی طور پر یہ معاشرے میں احساسِ محرومی اور دکھاوے کی دوڑ پیدا کرتا ہے۔ یہ وہی سوچ ہے جو کامیابی کو دولت کے اظہار سے جوڑتی ہے، کردار یا خدمت سے نہیں۔
قابلِ تعریف بات یہ ہے کہ صحیفہ نے اپنی ماضی کی ممکنہ غلطیوں کا بھی اعتراف کیا اور کہا کہ اگر کبھی ان کے الفاظ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو وہ شرمندہ ہیں۔ یہ خوداحتسابی کا وہ پہلو ہے جو آج کے سوشل میڈیا کلچر میں تقریباً ناپید ہو چکا ہے۔ دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے خود پر نظر ڈالنا ہی اصل مہذب رویہ ہے۔
ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ سوشل میڈیا صرف ایک “پلیٹ فارم” نہیں بلکہ ہمارے معاشرتی شعور کا آئینہ ہے۔ اگر ہم اس آئینے میں نفرت، تعصب اور غیر سنجیدگی دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارے اجتماعی رویوں کا عکس ہے۔ ذمہ داری صرف مواد بنانے والوں پر نہیں بلکہ دیکھنے، لائک کرنے اور شیئر کرنے والوں پر بھی ہے۔ اگر ہم غیر ذمہ دارانہ مواد کو نظرانداز کر دیں، اس پر ردعمل نہ دیں اور مثبت مکالمے کو فروغ دیں تو نفرت کا یہ کاروبار خود بخود سکڑ جائے گا۔
صحیفہ جبار خٹک کی تنقید دراصل ایک پیغام ہے کہ ہمیں اپنے الفاظ، رویوں اور آن لائن موجودگی کے بارے میں زیادہ سنجیدہ ہونا ہوگا۔ کیونکہ جو کچھ ہم لکھتے یا کہتے ہیں، وہ نہ صرف دوسروں کو متاثر کرتا ہے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی مثال قائم کرتا ہے۔ اگر ہم نے آج اس زہر کو روکنے کے لیے اقدام نہ کیا تو کل ہماری سوسائٹی اس کے اثرات سے نکل نہیں پائے گی۔
سوال یہ نہیں کہ سوشل میڈیا برا ہے یا اچھا — اصل سوال یہ ہے کہ ہم اسے کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس کا جواب ہم سب کو اپنے اپنے ضمیر سے لینا ہوگا۔
معاشی بحالی اور مہنگائی کا سایہ — شفافیت ہی اعتماد کی کنجی ہے
پاکستان کی معیشت کے بارے میں حالیہ اعداد و شمار اور مرکزی بینک کے اندازے بظاہر امید افزا ہیں۔ مالی سال 2026 کے لیے شرحِ نمو 3.5 سے 4.25 فیصد کے درمیان رہنے کی توقع ہے، بڑے پیمانے کی صنعت (LSM) میں سرگرمی کی واپسی کے آثار ہیں، ترسیلاتِ زر 40 ارب ڈالر سے تجاوز کرنے کی پیش گوئی کی جا رہی ہے، اور زرمبادلہ کے ذخائر جون تک 17.5 ارب ڈالر تک پہنچنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ طویل عرصے سے پاکستان کی بیرونی پوزیشن پر شکوک رکھنے والی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیاں بھی اب ملک کی ریٹنگ بہتر کر رہی ہیں۔
یہ سب ایک خوش آئند خبر ہے، مگر معاشی بحالی کی یہ تصویر ایک اہم پہلو کو نظرانداز نہیں کر سکتی — مہنگائی۔ اب یہ خطرہ صرف آزاد ماہرین یا مارکیٹ تجزیہ کاروں تک محدود نہیں رہا، بلکہ خود اسٹیٹ بینک بھی تسلیم کر رہا ہے کہ مہنگائی کا دباؤ اس کے 5-7 فیصد کے ہدف سے وقتی طور پر اوپر جا سکتا ہے۔ یہ اعتراف اس لیے اہم ہے کہ پہلے کی بریفنگز میں اسے تسلیم نہیں کیا گیا تھا، اور یہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب غیر ملکی زرمبادلہ کی منڈی میں مرکزی بینک کے کردار پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔
واضح ہو چکا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے جون 2024 سے اپریل 2025 کے دوران مقامی فارن ایکسچینج مارکیٹ سے 7.2 ارب ڈالر سے زائد خریدے۔ اس میں سے ایک ارب ڈالر سے بھی کم ذخائر میں شامل ہوا، جبکہ باقی زیادہ تر بیرونی قرضوں کی ادائیگی میں استعمال ہوا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ ڈالر کیسے خریدے گئے؟ اگر ان خریداریوں کے لیے روپے مارکیٹ میں ڈالے گئے اور انہیں واپس کھینچنے کے اقدامات (sterilisation) نہیں کیے گئے، تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ زرِمبادلہ بڑھانے کی قیمت روپے کی فراہمی میں اضافے کی شکل میں چکائی گئی — اور یہی مہنگائی کے دباؤ کو مستقل رکھنے کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ پالیسی ریٹ میں 1,100 بیسس پوائنٹس کی نمایاں کمی کے باوجود بنیادی مہنگائی (core inflation) کم نہیں ہو رہی۔ مزید تشویش اس بات پر ہے کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی (MPC) کی حالیہ بریفنگ میں اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں دی گئی کہ آیا یہ فارن ایکسچینج مداخلتیں اوپن مارکیٹ آپریشنز یا دیگر لیکویڈیٹی کنٹرول کے اقدامات سے متوازن کی گئیں یا نہیں۔
مہنگائی کا تعلق صرف اعداد و شمار سے نہیں بلکہ توقعات سے بھی ہے۔ جب مارکیٹ دیکھتی ہے کہ اسٹیٹ بینک ڈالر خرید رہا ہے اور ذخائر بنا رہا ہے، تو اسے یہ بھی نظر آنا چاہیے کہ ان خریداریوں کو مہنگائی میں بدلنے سے روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بصورتِ دیگر، عوام یہ فرض کر لیں گے کہ ذخائر بڑھانے کا یہ عمل دراصل روپے کی قدر گھٹانے اور قوتِ خرید کو متاثر کرنے کے ذریعے ہو رہا ہے۔
یہ درست ہے کہ معیشت میں کچھ مثبت اشارے نمایاں ہیں — مشینری اور درمیانی اشیا کی درآمدات میں اضافہ سرمایہ کاری کی بحالی کا عندیہ دیتا ہے، اور ذخائر اب ملک کی سالانہ خالص قرض ادائیگیوں سے زیادہ ہیں، جو ماضی میں ایک بڑی کمزوری تھی۔ لیکن یہ پیش رفت تبھی پائیدار سمجھی جائے گی جب اس کے ساتھ جڑے خطرات کو کھلے عام تسلیم اور حل کیا جائے۔
ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 2022-24 کی مہنگائی کا زلزلہ ابھی زیادہ پرانا نہیں۔ صرف دو سال پہلے ہی مجموعی مہنگائی 30 فیصد سے تجاوز کر گئی تھی، جس نے گھرانوں کے بجٹ کو تہس نہس کر دیا اور مانیٹری پالیسی کو ہنگامی سطح تک سخت کرنا پڑا۔ اس لیے کوئی بھی پالیسی — چاہے اس کا مقصد کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو — اگر دوبارہ اس زخم کو کھرچنے کا خطرہ رکھتی ہے، تو اس پر خاموشی کے بجائے کھل کر بحث ہونی چاہیے۔
آج کا اصل چیلنج امید اور حد سے بڑھی ہوئی خود اعتمادی کے بیچ کی لکیر کو پہچاننا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے زرعی پیداوار، بیرونی تجارت اور ترسیلات میں ممکنہ خطرات کا اعتراف کیا ہے، لیکن اسے اپنی حالیہ پالیسی مداخلتوں، خاص طور پر وہ جو مہنگائی پر اثر ڈال سکتی ہیں، کے بارے میں شفافیت اختیار کرنی ہوگی۔ اگر فارن ایکسچینج خریداریوں کو مؤثر طریقے سے (sterilise‘‘ کیا گیا ہے تو عوام کو اس کی تفصیل دی جائے؛ اگر نہیں، تو مانیٹری پالیسی میں اس خطرے کو واضح طور پر شامل کیا جائے۔
معاشی بحالی کی خوشی میں ممکنہ خطرات کو نظرانداز کرنا سب سے بڑی پالیسی غلطی ہو سکتی ہے۔ مثبت اشاروں کا خیرمقدم کرتے ہوئے ان کے ساتھ جڑی قیمت پر سوال اٹھانا دراصل بہتر پالیسی کے لیے ضروری دباؤ پیدا کرتا ہے۔ اس دباؤ کو نظرانداز کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنی معیشت کو ایک بار پھر ایسے مہنگائی کے بحران کے دہانے پر لے جائیں، جس سے نکلنے میں سالوں لگ سکتے ہیں۔
اس بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان کی معیشت میں اعتماد کی بحالی صرف اعداد و شمار یا وقتی بہتری سے ممکن نہیں بلکہ پالیسیوں کی مستقل مزاجی، شفافیت اور ادارہ جاتی خودمختاری اس کا بنیادی حصہ ہیں۔ جب اسٹیٹ بینک جیسے ادارے اپنی مداخلتوں کے بارے میں کھلے انداز میں وضاحت دیتے ہیں تو مارکیٹ کو ایک واضح سگنل ملتا ہے کہ فیصلے ڈیٹا پر مبنی ہیں اور ان کے ممکنہ اثرات کو مدِنظر رکھا گیا ہے۔ اس شفافیت کے بغیر سرمایہ کار، کاروباری حلقے اور عوام سب ایک طرح کے “پالیسی سرپرائز” کے خدشے میں رہتے ہیں، جو نہ صرف معیشت بلکہ مالیاتی منڈیوں میں بھی غیر یقینی کو بڑھاتا ہے۔
مزید یہ کہ، مہنگائی کے بارے میں توقعات کا درست انتظام (inflation expectations management) کسی بھی مانیٹری پالیسی کا اہم جزو ہوتا ہے۔ اگر عوام اور کاروباری حلقوں کو یہ یقین نہ ہو کہ مہنگائی قابو میں رہے گی تو وہ اپنی قیمتوں، اجرتوں اور سرمایہ کاری کے فیصلوں میں اسی خوف کو شامل کر لیں گے، جو بالآخر مہنگائی کو خود ہی بڑھا دیتا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی حالیہ پیش گوئی میں جب یہ کہا گیا کہ مہنگائی ہدف سے اوپر جا سکتی ہے، تو اس کے ساتھ یہ وضاحت نہ دینا کہ اس خطرے کو کم کرنے کے لیے کون سے عملی اقدامات کیے جائیں گے، ایک کمی محسوس ہوئی۔
یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شرح نمو میں اضافے کے ابتدائی آثار اکثر نازک ہوتے ہیں۔ بڑے صنعتی شعبے (LSM) میں پیداوار بڑھنا یا مشینری کی درآمدات کا بڑھنا اس بات کا عندیہ ہے کہ سرمایہ کاری کا عمل حرکت میں آ رہا ہے، لیکن اگر مہنگائی اس رفتار سے آگے نکل جائے تو یہ سرمایہ کاری جلد ہی مہنگے قرض، بلند پیداواری لاگت اور کمزور طلب کے بوجھ تلے دب سکتی ہے۔ یوں مختصر مدت کی بہتری ایک طویل مدتی جمود میں بدل سکتی ہے۔
فارین ایکسچینج کے ذخائر کی بحالی بھی اپنی جگہ ایک اہم کامیابی ہے، لیکن اگر یہ بحالی مقامی کرنسی کے پھیلاؤ اور مہنگائی کی قیمت پر حاصل کی جائے تو یہ کامیابی دیرپا نہیں رہ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ “sterilisation” جیسے اقدامات — یعنی مارکیٹ سے اضافی روپے واپس کھینچنا — نہ صرف تکنیکی ضرورت ہیں بلکہ پالیسی بیانیے کا حصہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اس وضاحت سے مارکیٹ میں اعتماد بڑھتا ہے کہ پالیسی ساز ایک طرف ذخائر بنا رہے ہیں اور دوسری طرف مہنگائی کو بھی قابو میں رکھ رہے ہیں۔
آگے بڑھتے ہوئے، حکومت اور اسٹیٹ بینک دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاشی بیانیے میں “یک طرفہ خوش خبری” کے بجائے “متوازن حقیقت” پیش کریں۔ عوام کو یہ بتانا کہ معیشت میں بہتری آ رہی ہے، درست ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی تسلیم کرنا کہ خطرات ابھی باقی ہیں، نہ صرف سنجیدہ طرزِ حکمرانی کی علامت ہے بلکہ اس سے پالیسی پر اعتماد بھی بڑھتا ہے۔
آخر میں، یہ بات تسلیم کرنا ہوگی کہ پاکستان نے گزشتہ چند برسوں میں شدید معاشی طوفان جھیلا ہے — بلند ترین مہنگائی، زرمبادلہ کے ذخائر کی کمی، قرضوں کا دباؤ، اور معاشی سست روی۔ اب جبکہ حالات میں کچھ بہتری کے آثار ہیں، یہ وقت پالیسی غلطیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ خوش فہمی اور خاموشی سے بڑھ کر، ہمیں دیانت دار مکالمہ، شفاف پالیسی وضاحت اور فوری اصلاحی اقدامات کی ضرورت ہے، تاکہ آج کی بہتری کل کے بحران میں نہ بدل جائے۔