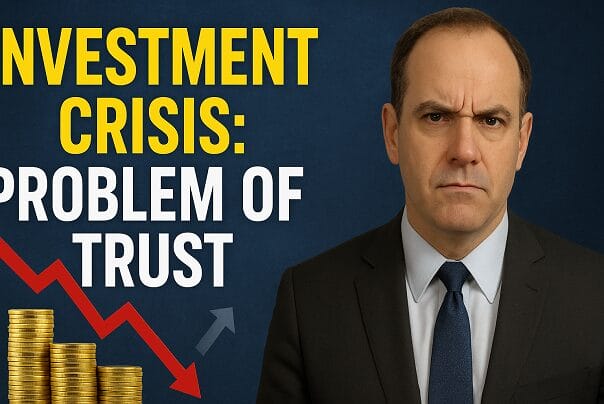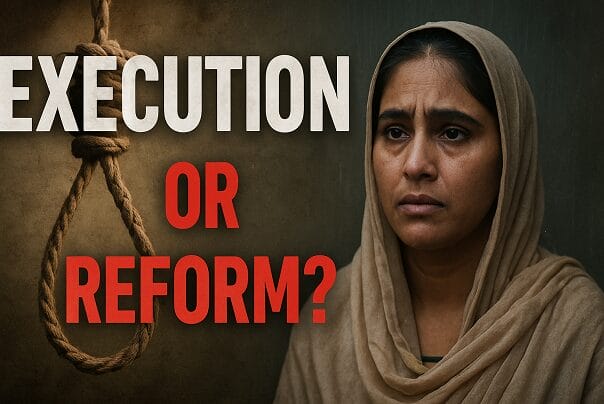پاکستان اور امریکہ کے درمیان حالیہ تجارتی و ٹیرف معاہدہ کئی دہائیوں پر محیط اتار چڑھاؤ سے بھرپور تعلقات میں ایک نئے موڑ کی علامت بن کر سامنے آیا ہے۔ دونوں ممالک نے اسے باضابطہ طور پر ’’نئے دور کی ابتدا‘‘ قرار دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نہ صرف معاہدے کا خیرمقدم کیا بلکہ اس کے ذریعے پاکستان کے ’’وسیع تیل کے ذخائر‘‘ تک رسائی حاصل کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس شراکت داری کے لیے جلد ایک امریکی تیل کمپنی کا انتخاب کریں گے جو اس منصوبے کی قیادت کرے گی۔
پاکستانی وزارتِ خزانہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق یہ معاہدہ توانائی، معدنیات، آئی ٹی، کرپٹو کرنسی اور دیگر جدید شعبہ جات میں دو طرفہ تعاون کے ایک نئے باب کی نوید ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اسے ایک ’’ون-ون ڈیل‘‘ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس معاہدے کا مقصد محض تجارتی رکاوٹوں کو دور کرنا نہیں بلکہ سرمایہ کاری کو فروغ دینا اور طویل المدتی اقتصادی اشتراک قائم کرنا ہے۔
تاہم ابھی تک معاہدے کی تفصیلات واضح نہیں کی گئیں، خاص طور پر وہ پہلو جو واشنگٹن کی جانب سے پاکستان پر عائد 29 فیصد تک کے ممکنہ ٹیرف سے متعلق ہیں۔ اگرچہ یہ ’’لبریشن ڈے ڈیوٹیز‘‘ فی الحال 90 دن کے لیے معطل کی گئی تھیں تاکہ مذاکرات کا موقع فراہم کیا جا سکے، لیکن یہ تعطل وقتی ہے۔ اس تناظر میں پاکستان کی یہ توقع کہ ٹیرف 15 سے 20 فیصد تک لایا جائے — یعنی جاپان، انڈونیشیا، فلپائن اور ویتنام جیسے دیگر امریکی تجارتی شراکت داروں کے برابر — نہایت اہم ہے۔
یہ بھی دلچسپ اتفاق ہے کہ اس اعلان سے ایک دن قبل صدر ٹرمپ نے بھارت پر روسی تیل کی خریداری پر ردعمل کے طور پر 25 فیصد درآمدی محصولات عائد کیے، جس سے اس پاک-امریکہ معاہدے کی علامتی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ اس وقت جب دنیا تجارتی بلاکس میں بٹ رہی ہے، ایسے میں پاکستان کا کسی بڑی عالمی معیشت کے ساتھ تجارتی تعاون کا آغاز، خواہ محدود ہی کیوں نہ ہو، ایک مثبت اشارہ ہے۔اس ابتدائی اعلان سے جو پیغام نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک، جو ماضی میں زیادہ تر سیکیورٹی یا انسدادِ دہشت گردی کی بنیاد پر تعلقات قائم رکھتے تھے، اب تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی شراکت داری کو ترجیح دینا چاہتے ہیں۔ اگر یہ تبدیلی محض وقتی نہ ہو اور مستقل حکمت عملی کا حصہ بنے، تو یہ پاکستان کی معیشت، برآمدات اور بین الاقوامی تجارتی وقار کے لیے خوش آئند ثابت ہو سکتی ہے۔
اگرچہ معاہدے کی تفصیلات ابھی غیر واضح اور مبہم ہیں، لیکن کچھ اشارے اہم معاشی اور سیاسی مضمرات رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے، یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی منڈی ہے، اور ایسے میں 29 فیصد تک ممکنہ درآمدی محصولات پاکستانی برآمدات کے لیے ایک سخت دھچکا ثابت ہو سکتے تھے۔ اگر پاکستان اس معاہدے کے تحت ان ٹیرف کو کم کرانے میں کامیاب ہوتا ہے — جیسا کہ حکام کی امید ہے — تو یہ نہ صرف پاکستان کی برآمدی صنعت کے لیے ریلیف ہو گا بلکہ تجارتی توازن کو مستحکم کرنے میں بھی مددگار ہوگا۔
تاہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ معاہدہ حقیقی اقتصادی ترقی کی بنیاد بنے گا یا محض ایک وقتی سیاسی مفاہمت کا نتیجہ ہے؟ امریکی صدر کی جانب سے پاکستانی تیل ذخائر میں دلچسپی کا اظہار، اور کسی امریکی کمپنی کو ان ذخائر کی تلاش اور ترقی کا قائد بنانا، پاکستان کے لیے مواقع کے ساتھ ساتھ احتیاط کا بھی متقاضی ہے۔ پاکستان کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ قدرتی وسائل پر اس کی خودمختاری برقرار رہے، اور معاہدوں میں شفافیت، ماحولیاتی تحفظ، اور مقامی مفاد کو مکمل تحفظ دیا جائے۔
اس موقع پر ایک اور پہلو بھی قابلِ غور ہے: معاہدے میں جن شعبہ جات — جیسے آئی ٹی، کرپٹوکرنسی اور معدنیات — کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں تعاون کی نوعیت اور قانونی فریم ورک پر کوئی تفصیل موجود نہیں۔ کرپٹو جیسے حساس اور ابھرتے ہوئے شعبے میں کسی بین الاقوامی شراکت سے پہلے اندرونِ ملک جامع پالیسی، ضابطہ کار ادارے، اور قانونی تحفظات کی ضرورت ہوگی، تاکہ کسی بھی مالیاتی یا سائبر خطرے سے بچا جا سکے۔
اس کے علاوہ، ایک بنیادی خدشہ یہ بھی ہے کہ کہیں یہ معاہدہ محض امریکی مفادات کو تحفظ دینے اور جغرافیائی سیاسی دباؤ سے نکلنے کی ایک چال تو نہیں؟ بھارت پر عائد حالیہ محصولات اور اس کے ساتھ امریکی کشیدگی کے پس منظر میں، پاکستان کے ساتھ تجارتی قربت محض متبادل اثر و رسوخ حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے پاکستان کو اپنی خارجہ اور تجارتی پالیسی میں تدبر، توازن اور خود مختاری کو مقدم رکھنا ہوگا۔
اب جبکہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدے کی ابتدائی بنیاد رکھی جا چکی ہے، تو یہ لمحہ محض خوشی کا نہیں بلکہ سنجیدہ تدبر اور جامع تیاری کا بھی ہے۔ کسی بھی بڑے بین الاقوامی معاہدے میں مواقع اور خطرات ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستانی پالیسی ساز محض فوری فائدے یا علامتی کامیابیوں پر اکتفا نہ کریں بلکہ اس شراکت داری کو قومی مفادات کے دائرے میں پرکھیں۔
معاہدے کے مثبت پہلوؤں میں سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ اگر امریکہ پاکستانی برآمدات پر عائد ٹیرف کو کم کرتا ہے تو اس سے پاکستانی ٹیکسٹائل، فارما، چمڑے اور انجینئرنگ مصنوعات کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری پیداواری صنعت کے لیے نئی زندگی بن سکتی ہے، بشرطیکہ مقامی سطح پر پیداواری لاگت، توانائی کی قیمتوں اور رسد کے ڈھانچے میں اصلاحات بھی کی جائیں۔ بصورتِ دیگر، عالمی منڈی تک رسائی کے باوجود پاکستان مقابلے کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے گا۔
اسی طرح، اگر توانائی، معدنیات اور آئی ٹی جیسے شعبوں میں امریکی سرمایہ کاری پاکستان آتی ہے تو یہ تکنیکی مہارت، ملازمتوں کے مواقع، اور انفراسٹرکچر کی ترقی کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ لیکن ان شعبوں میں معاہدے کرتے وقت ہمیں اپنی شرائط پر بات کرنی ہوگی۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسے کئی مواقع رہے ہیں جب بیرونی سرمایہ کاری نے مقامی مفادات کو پسِ پشت ڈال دیا۔ اس تجربے کی روشنی میں موجودہ معاہدے کے ہر پہلو کی پارلیمانی نگرانی، شفافیت اور احتساب کو یقینی بنانا ہوگا۔
آخری بات جو خاص اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس معاہدے کو صرف امریکہ پر انحصار کے تناظر میں نہیں بلکہ ایک متوازن اور خودمختار خارجہ پالیسی کے زاویے سے دیکھنا ہوگا۔ ہمیں امریکہ، چین، یورپی یونین، خلیجی ممالک اور دیگر عالمی طاقتوں کے ساتھ تعلقات میں ایسا توازن رکھنا ہوگا کہ کوئی ایک تعلق دوسرے پر اثر انداز نہ ہو۔
یہ معاہدہ اگر دانشمندی، شفافیت اور قومی مفاد کو مدِنظر رکھتے ہوئے مکمل کیا گیا تو یہ واقعی پاک-امریکہ تعلقات میں ایک نیا باب بن سکتا ہے — ایسا باب جو صرف تجارت اور معیشت ہی نہیں، بلکہ خودمختاری، ترقی اور قومی وقار کی نئی تعریف وضع کرے گا۔ اگر ایسا نہ ہوا، تو یہ موقع بھی ماضی کی دیگر وقتی مفاہمتوں کی طرح تاریخ کی نظر ہو جائے گا۔
ماحولیاتی تبدیلی: کم دنوں میں زیادہ بارش
پاکستان میں جاری مون سون بارشیں اور ان کے نتیجے میں آنے والے سیلاب اب صرف ایک قدرتی آفت نہیں رہے، بلکہ ایک نئے موسمیاتی عہد کی علامت بن چکے ہیں۔ صدیوں پرانے مون سون نظام کی پیش گوئی کی بنیادیں اب متزلزل ہو چکی ہیں۔ جن علاقوں میں ماضی میں شدید بارشیں معمول تھیں، اب وہ نسبتاً خشک ہیں، اور جہاں کبھی ہلکی بارشیں ہوتی تھیں، وہاں اب ریکارڈ توڑ موسمی شدت دیکھی جا رہی ہے۔ پاکستان اس بدلتے ہوئے ماحولیاتی منظرنامے کے مرکز میں ہے — اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری پالیسی، تیاری، اور انفراسٹرکچر ابھی تک پرانے سانچوں میں ڈھلے ہوئے ہیں۔
تحقیق بتاتی ہے کہ اگرچہ بارش کی شدت کئی گنا بڑھ گئی ہے، مگر برسات کے دنوں کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ یعنی کم دنوں میں زیادہ بارش، اور اس کا مطلب ہے زیادہ نقصان، کم تیاری، اور شدید دباؤ کا شکار مقامی نظام۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بارشوں کا جغرافیائی پھیلاؤ بھی تبدیل ہو چکا ہے۔ شمالی پہاڑی علاقوں کی نسبت اب جنوبی صوبے بارشوں کی زد میں زیادہ آ چکے ہیں — سندھ، جنوبی پنجاب، بلوچستان اور کوہِ سلیمان جیسے علاقے حالیہ برسوں میں شدید بارشوں اور سیلابوں کی زد میں آئے ہیں۔ یہ تبدیلی نہ صرف سیلابی خطرات کی نوعیت کو بدل رہی ہے بلکہ ہمارے موجودہ اداروں اور پالیسیوں کی مطابقت کو بھی چیلنج کر رہی ہے۔
علاقائی بنیادوں پر اگر دیکھا جائے تو غیر دریاوی (non-riverine) سیلاب اب ملک بھر میں ایک نیا اور خطرناک رجحان بن چکے ہیں۔ کراچی ہو یا لاہور، چکوال ہو یا راجن پور — شدید اور مقامی بارشیں اچانک نالوں، گلیوں، اور آبادیوں کو ڈبو دیتی ہیں۔ 2025 کی حالیہ مون سون میں چکوال میں 10 گھنٹوں کے دوران 400 ملی میٹر بارش ہوئی — ایک تباہ کن منظر جس کا کوئی مؤثر قبل از وقت انتباہ نہیں دیا گیا۔ بدقسمتی سے، ہمارا موجودہ فلیش فلڈ وارننگ سسٹم محدود، کمزور اور اکثر ناقابلِ اعتبار ہے۔
مزید خطرہ اچانک آنے والی “کلاؤڈ برسٹس” سے ہے — وہ شدید بارشیں جو چند لمحوں میں زمین کو پانی میں ڈبو دیتی ہیں۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا جیسے خطوں میں ان واقعات کی شرح میں واضح اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اس کے باوجود اکثر حکام ہر بھاری بارش کو “کلاؤڈ برسٹ” قرار دے کر خود کو بنیادی انتظامی ناکامی سے بری الذمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے سائنسی و انتظامی اعتبار کی کمی پیدا ہوتی ہے۔ ایسا رویہ نہ صرف نکتہ رسی کو کمزور کرتا ہے بلکہ انشورنس اور خطرے کے منتقلی کے جدید طریقوں کو متعارف کرانے کی کوششوں کو بھی ناکام بنا دیتا ہے۔
کوہِ سلیمان کا پہاڑی سلسلہ اب فلیش فلڈز کا نیا منبع بنتا جا رہا ہے، جس کی لپیٹ میں جنوبی پنجاب کے اضلاع ڈیرہ غازی خان اور راجن پور شدید متاثر ہوئے ہیں۔ 2022 اور 2024 کے دوران لاکھوں ایکڑ زمین زیرِ آب آئی، ہزاروں خاندان بے گھر ہوئے، اور بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا۔ یہ صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ ان علاقوں میں قدرتی حل (nature-based solutions) جیسے کہ مصنوعی جھیلوں، واٹر ریچارج زونز اور سیلابی پانی کو محفوظ بنانے کے نظام متعارف کرائے جائیں — نہ کہ صرف ایمرجنسی امداد اور وقتی بندوبست پر انحصار کیا جائے۔
شہری سیلاب اب کسی حادثے کا نہیں، ایک متوقع المیے کا روپ دھار چکے ہیں۔ کراچی، لاہور، راولپنڈی اور اسلام آباد جیسے شہر بار بار ایسے طوفانی مناظر کا سامنا کر رہے ہیں جن میں سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی شہری آبادی، ناقص منصوبہ بندی، غیر مؤثر نکاسی آب کا نظام، اور غیر منظم تجاوزات نے اس مسئلے کو سنگین تر بنا دیا ہے۔ شدید گرمی، جو شہری علاقوں میں “اربن ہیٹ آئی لینڈ ایفیکٹ” پیدا کرتی ہے، بارش کی شدت میں مزید اضافہ کرتی ہے، اور یوں شہری سیلاب کا دورانیہ اور شدت دونوں بڑھتے جا رہے ہیں۔
پاکستان کو اس وقت دوہرے ماحولیاتی خطرے کا سامنا ہے — شدید گرمی اور اس کے فوراً بعد تباہ کن بارشیں۔ ایک جانب درجہ حرارت میں اضافے سے مٹی کی پانی جذب کرنے کی صلاحیت 40 سے 60 فیصد تک کم ہو جاتی ہے، جس سے بارش کا پانی زمین میں جذب ہونے کے بجائے سطح پر بہہ کر سیلاب کی صورت اختیار کرتا ہے۔ دوسری جانب، ایک بار مٹی مکمل طور پر سیراب ہو جائے تو اگلی بارش پانی کو جذب کرنے کی گنجائش نہیں چھوڑتی، یوں مسلسل بارشوں کی صورت میں ہر نیا سلسلہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔
ان حالات میں پاکستان کے لیے روایتی “دریائی سیلاب” کی منصوبہ بندی اب ناکافی ہے۔ ہمیں فوری طور پر اپنی پالیسیوں میں موسمیاتی سائنسی تجزیے کو شامل کرنا ہوگا، ضلعی سطح پر ڈیزاسٹر مینجمنٹ اداروں کو خودمختار، مؤثر اور مقامی بنایا جائے، شہری ڈرینیج نظام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے، اور کوہِ سلیمان، سالٹ رینج، اور بارانی علاقوں میں مقامی سطح کے فطری اقدامات اختیار کیے جائیں۔
اگر ہم آج سے تیاری شروع نہ کریں تو کل یہ موسمیاتی بحران ہماری معیشت، خوراک، نقل مکانی، اور بقاء کے لیے ایک مستقل خطرہ بن جائے گا — اور پھر ہم صرف اعداد و شمار پر بحث کریں گے، حل نہیں نکال سکیں گے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اس “نئے معمول” کو تسلیم کریں اور اُس کے مطابق اپنے انفراسٹرکچر، منصوبہ بندی، اور طرزِ حکمرانی میں بنیادی تبدیلی لائیں۔
انسانیت زندہ ہے
کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسانیت، اپنے سب سے نازک لمحے میں، سب سے روشن روپ اختیار کر لیتی ہے۔ ایسا ہی ایک لمحہ پاکستان نے اس وقت دیکھا جب 23 سالہ سلطان ظفر کے انتقال کے بعد، ان کی والدہ ڈاکٹر مہر افروز نے — جو خود اسی ادارے (SIUT) کی معالج ہیں — اپنے جواں سال بیٹے کے گردے دو اجنبی مریضوں کو عطیہ کر دیے۔ یہ فیصلہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ اپنے بیٹے کی موت جیسے ناقابلِ تصور دکھ میں، کسی اور کی زندگی بچانے کا فیصلہ صرف وہی کر سکتا ہے جو ایثار، رحم اور عظمتِ انسانیت کا حقیقی پیکر ہو۔
ڈاکٹر مہر افروز کا یہ عمل ہمیں نہ صرف سوگ اور محرومی کے مفہوم پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرتا ہے بلکہ یہ سوال بھی اٹھاتا ہے کہ ہم، بطور معاشرہ، اس بے مثال قربانی کو معمول کا حصہ بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ حالیہ دنوں میں ڈان کی سابقہ رکن زبیدہ مصطفیٰ کی جانب سے اپنی آنکھیں عطیہ کرنے کا عمل بھی اسی تسلسل کی ایک اور درخشاں مثال ہے — انفرادی فیصلے، جو کئی زندگیاں بدل دیتے ہیں۔
یہ ایسے واقعات ہیں جو صرف جذباتی نہیں بلکہ اجتماعی طور پر بیداری کے تقاضا کرتے ہیں۔ خوش آئند ہے کہ حکومت نے گزشتہ برس قومی شناختی کارڈز پر اُن افراد کے لیے خصوصی لوگو شامل کرنے کا اعلان کیا جو اپنی زندگی کے بعد اعضاء عطیہ کرنے کے خواہش مند ہیں۔ یہ قدم بلاشبہ اہم ہے، لیکن کافی نہیں۔ ہمیں اعضاء عطیہ کرنے کی ثقافت کو معاشرے میں “غیر معمولی” سے “عام” بنانا ہوگا۔
سب سے پہلے، معلومات کی رسائی کو آسان بنایا جائے۔ اسپتالوں، کلینکس اور نادرا دفاتر میں رجسٹریشن کا طریقہ کار واضح اور قابلِ فہم ہونا چاہیے۔ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر علاقائی زبانوں میں بھرپور مہم چلائی جائے تاکہ ہر فرد کو یہ شعور حاصل ہو کہ وہ اپنی موت کے بعد بھی زندگیاں بچا سکتا ہے۔
علمائے کرام نے پہلے ہی واضح کر دیا ہے کہ اعضاء کا عطیہ دینا صدقہ جاریہ ہے — اور یہ پیغام مسلسل دہرایا جانا چاہیے تاکہ مذہبی شکوک و شبہات کو جڑ سے ختم کیا جا سکے۔ اسی طرح ڈاکٹروں کو بھی یہ تربیت دی جائے کہ وہ مریضوں اور ان کے اہلِ خانہ سے یہ گفتگو نہایت حساسیت سے کریں، کیونکہ بسا اوقات صرف صحیح وقت پر کی گئی بات ہی کسی کو فیصلہ کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے۔
ہر عطیہ دہندہ اپنی زندگی کے بعد آٹھ لوگوں کو نئی زندگی دے سکتا ہے، اور کئی مزید افراد کے لیے بصارت، حرکت یا صحت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اگر سلطان ظفر کے اہلِ خانہ، شدید ترین ذاتی صدمے کے باوجود، یہ فیصلہ کر سکتے ہیں تو ہم باقی کیوں نہیں؟
یہ وقت ہے کہ معاشرہ اجتماعی طور پر اپنی ہچکچاہٹ ترک کرے، اور عطیہ اعضاء کو غیرمعمولی ایثار کے بجائے ایک فطری انسانی عمل تسلیم کرے۔ سلطان ظفر جیسے نوجوان اگر اپنی موت کے بعد بھی روشنی کا ذریعہ بن سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کے فیصلے کو خراج تحسین پیش کریں — اور ان کے نقشِ قدم پر چلنے کا عزم کریں۔
انسانیت واقعی زندہ ہے — سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہم بھی اس روشنی کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں؟
شرح سود میں استحکام — احتیاط یا ابہام؟
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے مانیٹری پالیسی کمیٹی -ایمپی سی کے حالیہ فیصلے میں شرح سود کو 11 فیصد پر برقرار رکھنے کا اعلان کئی حلقوں کے لیے غیر متوقع اور حیران کن ثابت ہوا ہے۔ معاشی اشاریے، بالخصوص کنزیومر پرائس انڈیکس -سی پی آئی اور بنیادی مہنگائی (core inflation) میں مسلسل کمی کے تناظر میں عمومی توقع یہ تھی کہ اس مرتبہ بھی شرح سود میں کمی کی جائے گی — جیسا کہ دسمبر 2024 سے مئی 2025 کے درمیان کئی مرتبہ کیا گیا۔
جہاں نومبر 2024 میں CPI 4.9 فیصد تھی، وہی اپریل 2025 تک کم ہو کر 0.3 فیصد پر آ گئی، اور جون میں بھی صرف 3.2 فیصد رہی۔ ساتھ ہی core inflation بھی مارچ سے مسلسل گھٹتی ہوئی جون میں 6.9 فیصد پر آ چکی ہے۔ ان اعداد و شمار کے باوجود، MPC کا شرح سود کو برقرار رکھنا اس تاثر کو مضبوط کرتا ہے کہ شاید مہنگائی اب شرح سود کے تعین میں بنیادی عنصر نہیں رہا — یا کم از کم اس پر عملدرآمد میں کوئی اور ترجیح حائل ہے۔
یہ بات اہم ہے کہ عالمی سطح پر اقتصادی سست روی کے باوجود، مانیٹری پالیسی بیان میں معیشت کے کئی پہلوؤں — جیسے گاڑیوں کی فروخت، کھاد کی طلب، مشینری کی درآمدات، اور نجی شعبے کو دیا گیا قرض — کو مثبت پیش رفت کے طور پر پیش کیا گیا۔ مگر تجزیہ نگاروں کے مطابق ان میں سے کئی اشاریے دراصل ذخائر کی کمی (inventory drawdown) یا روپے کی نسبتاً استحکام کی وجہ سے کم درآمدی لاگت کی عکاسی کرتے ہیں، نہ کہ صنعتی پیداوار یا حقیقی ترقی کی۔ مثلاً بڑی صنعتوں کی پیداوار (LSM) رواں مالی سال کے جولائی تا اپریل کے دوران منفی 1.52 فیصد رہی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں تنزلی کا اشارہ ہے۔
مزید برآں، اگرچہ مرکزی بینک نے پریس کانفرنس کے ذریعے فیصلے کی وضاحت کی — جس کی تعریف کی جانی چاہیے کیونکہ یہ عوامی اعتماد اور شفافیت کی طرف ایک قدم ہے — تاہم صنعتی برادری کو مطمئن کرنے میں یہ وضاحتیں ناکام رہی ہیں۔ معاشی پالیسی کی کامیابی صرف بیانات سے نہیں، بلکہ قابلِ فہم اور متوازن فیصلوں سے وابستہ ہے۔ جب اعداد و شمار ایک جانب اشارہ کریں اور پالیسی دوسری سمت اختیار کرے، تو اعتماد میں کمی فطری ردِ عمل بن جاتا ہے۔
آئی ایم ایف کی حالیہ سفارشات بھی اس فیصلے کے پس منظر میں اہم ہیں۔ فنڈ نے واضح کیا ہے کہ اگرچہ سی پی آئی میں کمی خوش آئند ہے، لیکن جب تک بنیادی افراط زر مستحکم انداز میں اسٹیٹ بینک کے مقرر کردہ ہدف کے دائرے میں نہیں آتی، مالیاتی نرمی احتیاط سے اور مرحلہ وار ہونی چاہیے۔ مزید برآں، منافع کی بیرون ملک منتقلی کی مالیاتی نرمی اور زرمبادلہ کے ذخائر کے ’’رول اوور‘‘ پر انحصار جیسے فیصلے شاید فنڈ کے تحفظات کا سبب بنے، جس کے تحت شرح سود میں مزید کمی کو روک دیا گیا۔
بظاہر یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے توانائی کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے، درآمدی اشیاء کی لاگت، اور حالیہ سیلاب کے زرعی اثرات کو مدِنظر رکھتے ہوئے ایک محتاط رویہ اختیار کیا ہے۔ تاہم یہ احتیاط اس وقت تک کارگر ثابت نہیں ہو سکتی جب تک اسے مؤثر ڈیٹا، شفاف جواز اور مارکیٹ کی ضروریات سے ہم آہنگ طریقے سے پیش نہ کیا جائے۔
ضرورت اس امر کی ہے کہ شرح سود جیسے اہم فیصلے وقتی مفروضات یا بیرونی دباؤ کی بجائے ٹھوس داخلی معاشی حقیقتوں اور مقامی صنعت کی نبض کے مطابق کیے جائیں۔ بصورتِ دیگر، کاروباری اعتماد، سرمایہ کاری کی رفتار اور معاشی بحالی کے امکانات سب متاثر ہو سکتے ہیں۔
اگر مہنگائی کی رفتار سست ہو رہی ہے، صنعت اور روزگار دباؤ میں ہیں، اور زرِ مبادلہ کی حالت اب بھی غیر یقینی ہے، تو مالیاتی پالیسی کو توازن، شفافیت اور تدبر کے ساتھ آگے بڑھایا جانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ صرف احتیاط کافی نہیں — پالیسیوں میں اعتماد، وضاحت اور یکسوئی بھی ناگزیر ہے۔