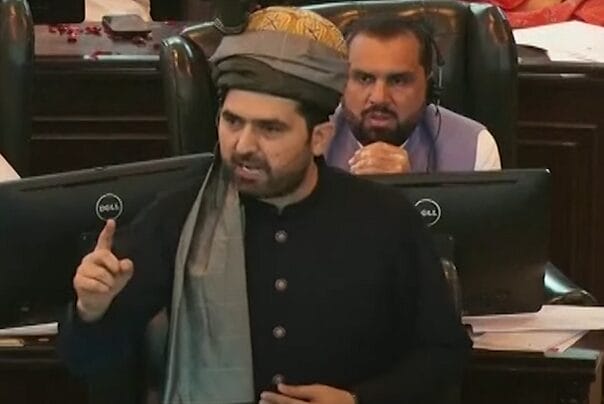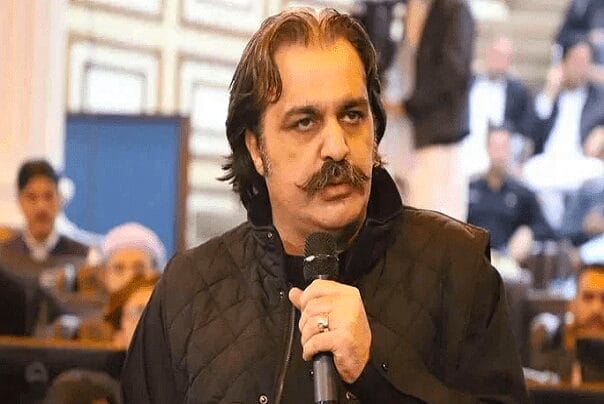پاکستان ایک بار پھر سیلاب کی شدید تباہ کاریوں سے گزر رہا ہے۔ محکمۂ موسمیات اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق رواں برس مون سون بارشوں کے نتیجے میں اب تک تقریباً 500 افراد جاں بحق، 9 لاکھ سے زائد لوگ متاثر، اور 80 ہزار کے قریب گھر مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ پنجاب اور سندھ کے کئی اضلاع میں دریاؤں کی طغیانی نے ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے۔ لیکن ان اعداد و شمار کے پیچھے محض قدرت کی سختی نہیں چھپی، بلکہ ہماری اجتماعی غفلت اور ماحول دشمن پالیسیوں کا ایک پورا سلسلہ ہے جسے آج دنیا “ماحول کُشی” (Ecocide) کہتی ہے۔ہم اکثر اپنی بدحالی کو صرف بارش اور قدرتی آفات کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ ہم نے خود اپنی زمین اور اپنے ماحول کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ بڑے شہروں کے گرد و نواح میں جتنے بھی ہاؤسنگ پروجیکٹس کھڑے کیے گئے، ان میں سے اکثریت یا تو دریاؤں کی قدرتی گزرگاہوں پر بنی ہیں یا نالوں اور برساتی راستوں کو بند کر کے۔ لاہور میں راوی کے کنارے واقع رہائشی اسکیمیں ہوں یا کراچی میں ندی نالوں پر بنی پوش ہاؤسنگ سوسائٹیاں—یہ سب مثالیں ہیں کہ کس طرح ہم نے فطرت کے راستوں کو مسدود کر کے اپنی ہی تباہی کا سامان تیار کیا۔سیلاب نے ایک بار پھر یہ حقیقت عیاں کر دی ہے کہ دریا اپنے راستے مانگتے ہیں، پانی کو پھیلنے کے لیے زمین چاہیے، اور بارش کو جذب ہونے کے لیے سبزہ زار اور جنگل درکار ہیں۔ اگر ہم یہ سب کچھ سیمنٹ اور کنکریٹ سے ڈھانپ دیں گے تو پانی شہر کی گلیوں اور بستیوں کو بہا لے جائے گا۔ یہی کچھ گزشتہ سال بھی ہوا جب 2022 کے تاریخی سیلاب نے ملک بھر میں 1700 سے زیادہ افراد کی جان لی اور تقریباً 3 کروڑ 30 لاکھ لوگوں کو متاثر کیا۔ اس سانحے کے بعد عالمی برادری نے پاکستان کے لیے امداد کا وعدہ کیا، مگر ہم نے اپنے اندرونی ڈھانچے اور ترقیاتی ماڈل پر کوئی بنیادی سوال اٹھانے کی زحمت نہیں کی۔ماحول کُشی کا یہ عمل صرف ڈویلپرز یا چند سرمایہ داروں تک محدود نہیں ہے۔ اس میں ایک اجتماعی شراکت داری موجود ہے۔ اوسط اور بالائی متوسط طبقہ اپنی رہائشی خواہشات پوری کرنے کے لیے ان اسکیموں کا حصہ بنتا ہے۔ یہ جانے بغیر کہ اس زمین کو کس طرح حاصل کیا گیا، کس کسان کو بے دخل کیا گیا، کتنے درخت اجاڑے گئے یا کس دریا کے راستے کو بند کیا گیا۔ پھر جب ان خوابوں کی بستیوں کو سیلاب بہا لے جاتا ہے تو ہم قدرت کو الزام دیتے ہیں، حالانکہ یہ قدرت کا نہیں، ہماری اپنی بے تدبیری کا نتیجہ ہوتا ہے۔تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے۔ ان اسکیموں کے اکثر مکین وہ لوگ ہیں جو شہروں کے اندر رہائش برداشت نہیں کر سکتے۔ پرانے محلوں کی بدحالی، پانی اور بجلی کی کمی، اور عدم تحفظ انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ نسبتاً سستی کالونیوں کی طرف رخ کریں۔ وہ خود بڑے مگرمچھ نہیں بلکہ سب سے چھوٹی مچھلیاں ہیں اس گندے تالاب میں۔ اصل کھیل ان سرمایہ کاروں اور ڈویلپرز کا ہے جو زمین کو محض منافع کے لیے خریدتے اور بیچتے ہیں۔ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق پاکستان میں شہری زمین کا 40 فیصد سے زائد حصہ رہائشی اسکیموں کے نام پر جمود کا شکار ہے—جہاں یا تو پلاٹ برسوں خالی پڑے ہیں یا محض سرمایہ کاری کے لیے رکھے گئے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ نہ تو اصل مکانات بنتے ہیں اور نہ ہی عام آدمی کو رہائش میسر آتی ہے۔اس پورے کھیل کا سب سے بڑا فریق ریاست ہے۔ فوجی اداروں کی جانب سے زمین بانٹنے کی روایت ہو، مقامی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی کرپشن اور نااہلی ہو، یا سیاست دانوں کی براہِ راست سرمایہ کاری—ریاست نے ماحول کُشی کو باقاعدہ سرپرستی فراہم کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج معمولی سا موسمی تغیر بھی بڑے پیمانے پر تباہی لاتا ہے کیونکہ ہم نے دریاؤں کے راستے تنگ کر دیے ہیں، برساتی پانی کے ذخیرے ختم کر دیے ہیں، اور زمین کے سانس لینے کی جگہ چھین لی ہے۔کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مقامی افسران اوپر سے دباؤ میں آ جاتے ہیں، یا یہ کہ سیاسی رہنما فوج کے سامنے بے بس ہیں۔ لیکن یہ تاویلیں حقیقت کو چھپا نہیں سکتیں۔ اصل ذمہ داری ریاست پر ہے، جس نے شعوری فیصلوں کے ذریعے ماحول کُشی کو جائز اور منافع بخش بنایا۔اب وقت آگیا ہے کہ ہم اجتماعی طور پر یہ تسلیم کریں کہ ماحول کُشی دراصل ایک اجتماعی جرم ہے۔ یہ صرف ایک درخت کاٹنے یا ایک دریا پر قبضہ کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنی آئندہ نسلوں کو زندگی کے حق سے محروم کرنے کا جرم ہے۔ اگر ہم نے اپنی پالیسیوں اور ترقیاتی منصوبوں میں ماحول کو بنیادی حیثیت نہ دی تو آنے والے برسوں میں قحط، خشک سالی اور مزید تباہ کن سیلاب ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن جائیں گے۔ہمارے منتخب نمائندوں سے توقع ہے کہ وہ عوامی مفاد کا خیال رکھیں گے۔ عوامی مفاد آج بالکل واضح ہے: زمین کے سماجی اور ماحولیاتی استحصال کو روکنا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دریاؤں کے کنارے سے تجاوزات ختم کی جائیں، برساتی نالوں کو کھولا جائے، زمین کو صرف تجارت کا مال بنانے کی بجائے رہائش اور ماحول کے توازن کے ساتھ استعمال کیا جائے۔حالیہ سیلاب ایک انتباہ ہے۔ اگر ہم نے اب بھی نہ سنبھالا تو آنے والے طوفان محض پانی کی لہریں نہیں ہوں گے بلکہ وہ ہماری اجتماعی غفلت اور بے حسی کا حساب بھی لے کر آئیں گے۔پاکستان میں ہر بڑے سیلاب یا زلزلے کے بعد سب سے زیادہ توجہ جس ادارے کی طرف جاتی ہے وہ ہے این ڈی ایم اے۔ یہ ادارہ 2010 کے تباہ کن سیلاب کے بعد غیر معمولی توقعات کے ساتھ سامنے آیا تھا، لیکن آج پندرہ برس بعد بھی اس کی کارکردگی سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے۔2022 کے سیلاب میں، جب ملک کا ایک تہائی حصہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا اور تقریباً 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ براہِ راست متاثر ہوئے تھے، این ڈی ایم اے کی ذمہ داری تھی کہ وہ فوری امدادی کارروائیوں سے لے کر طویل مدتی بحالی تک ایک واضح اور مربوط لائحہ عمل سامنے لاتا۔ مگر کیا ہوا؟ متاثرین خیموں اور کھلے آسمان تلے سسکتے رہے، خوراک اور ادویات کی کمی نے لاکھوں زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا، اور ریاستی مشینری زیادہ تر بین الاقوامی امداد کی اپیل کرنے تک محدود رہی۔رواں برس کے حالیہ سیلاب میں بھی یہی منظر سامنے آیا۔ این ڈی ایم اے کی رپورٹس میں اعداد و شمار تو باقاعدگی سے جاری کیے گئے—کہ کتنے لوگ جاں بحق ہوئے، کتنے بے گھر ہوئے، اور کتنی سڑکیں یا پل بہہ گئے—لیکن ان اعداد و شمار کے ساتھ کوئی مؤثر منصوبہ بندی نہیں جُڑی۔ متاثرین اب بھی مقامی کمیونٹیز اور فلاحی اداروں کے رحم و کرم پر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہر آفت کے وقت عوام کو غیر ریاستی فلاحی اداروں کی طرف ہی دیکھنا پڑے تو پھر اربوں روپے کے بجٹ اور درجنوں دفاتر رکھنے والی این ڈی ایم اے کا مقصد کیا ہے؟اصل مسئلہ یہ ہے کہ این ڈی ایم اے کا کردار زیادہ تر کاغذی کارروائی اور بیوروکریٹک رپورٹنگ تک محدود ہو گیا ہے۔ اس کے پاس نہ تو مقامی سطح پر فوری ردعمل دینے کی صلاحیت ہے اور نہ ہی وسائل۔ ضلعی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز (DDMAs) کاغذ پر تو موجود ہیں، مگر عمل میں ان کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ کسی گاؤں میں جب سیلاب آتا ہے تو سب سے پہلے مقامی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کشتیوں یا ٹریکٹر ٹرالیوں سے لوگوں کو بچاتے ہیں، اور این ڈی ایم اے کے عملے کا پتہ ہفتوں بعد چلتا ہے۔ایک اور سنگین پہلو یہ ہے کہ این ڈی ایم اے کی توجہ زیادہ تر ریلیف پر مرکوز ہے، پری وینشن (Prevention) یعنی آفات کو روکنے یا ان کے اثرات کو کم کرنے کے اقدامات پر نہیں۔ دنیا بھر میں جدید ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی بنیاد یہی ہے کہ آفات آنے سے پہلے حفاظتی اقدامات کیے جائیں:
• دریاؤں کے کنارے پر غیر قانونی تعمیرات ختم کی جائیں،
• برساتی نالوں کو کھلا رکھا جائے،
• جدید اربن پلاننگ کے ذریعے نکاسیٔ آب کا نظام بہتر بنایا جائے،
• اور جنگلات کی کٹائی روکی جائے۔
پاکستان میں یہ سب کچھ کرنے کے بجائے ہم ہر سال صرف یہ گنتی کرتے ہیں کہ کتنے لوگ ڈوب گئے اور کتنے گھر بہہ گئے۔این ڈی ایم اے کی ایک اور کمزوری اس کی شفافیت کی کمی ہے۔ اربوں روپے کی ملکی اور غیر ملکی امداد اس ادارے کے ذریعے گزرتی ہے، لیکن عوام کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ امداد کہاں خرچ ہوئی۔ 2022 کے سیلاب کے بعد عالمی برادری نے 9 ارب ڈالر سے زیادہ کی امداد کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس میں سے کتنا پیسہ کہاں لگا؟ کتنے اسکول یا اسپتال دوبارہ تعمیر ہوئے؟ کتنے پل اور سڑکیں بحال ہوئیں؟ یہ سوال آج بھی جواب طلب ہیں۔یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آفات کے وقت پاکستان میں سب سے بڑی کمی انسٹی ٹیوشنل اسٹریٹجی اور اکاؤنٹیبلٹی کی ہے۔ جب تک این ڈی ایم اے کو صرف اعداد و شمار جاری کرنے والے ادارے سے ایک فعال، مقامی سطح پر موجود اور جواب دہ ادارہ نہیں بنایا جائے گا، تب تک ہر سال سیلاب ہمیں اسی طرح بے بس کرے گا۔
پاکستان کو ایک نئے ماحول دوست ڈیزاسٹر مینجمنٹ ماڈل کی ضرورت ہے، جہاں:
• آفات کی روک تھام کو ریلیف پر فوقیت دی جائے،
• مقامی کمیونٹیز کو وسائل اور تربیت فراہم کی جائے،
• شفافیت اور آڈٹ کو یقینی بنایا جائے،
• اور سب سے بڑھ کر، پالیسی سازی میں ماہرینِ ماحولیات اور اربن پلانرز کو مرکزی کردار دیا جائے۔حالیہ سیلاب نے ہمیں پھر یاد دلایا ہے کہ صرف امداد بانٹنے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ اصل تبدیلی اس وقت آئے گی جب این ڈی ایم اے جیسے ادارے ماحول کُشی کو روکنے، فطرت کے راستے بحال کرنے، اور زمین کو سانس لینے کا حق دینے کی پالیسی پر عمل پیرا ہوں گے۔ ورنہ آئندہ آنے والا ہر سیلاب محض پانی کی لہریں نہیں ہوگا بلکہ ہماری اپنی نااہلی اور بے حسی کا حساب بھی ساتھ لائے گا۔