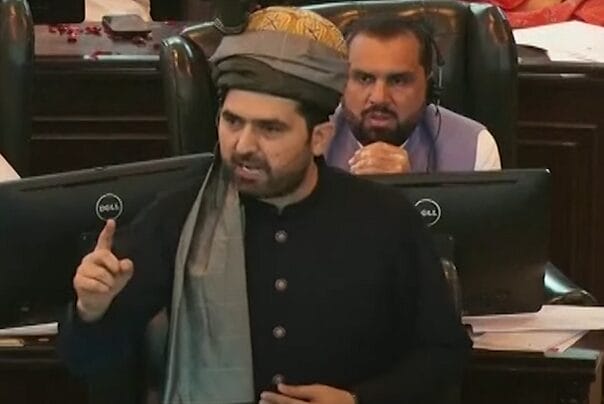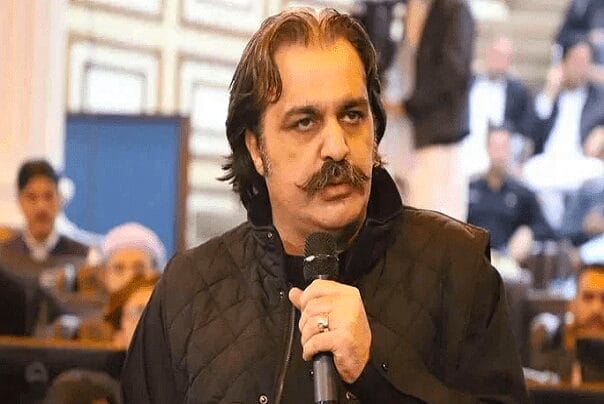پاکستان میں عدلیہ کو ایک زمانے تک سیاسی اور ادارہ جاتی بحرانوں میں روشنی کا مینار سمجھا جاتا رہا۔ جب پارلیمان مفلوج ہو جاتی تھی اور ایگزیکٹو اپنی آئینی حدود سے تجاوز کرتا تھا، تو نظریں عدلیہ کی جانب اٹھتی تھیں کہ وہ آئین کی تشریح کرے اور انصاف کے تقاضے پورے کرے۔ مگر آج صورتحال یکسر مختلف دکھائی دیتی ہے۔ عدلیہ، جو عوام کو رہنمائی دینے اور طاقت کے غیر متوازن ڈھانچے کو متوازن رکھنے کی ضامن تھی، خود ایک ایسے بحران میں گرفتار ہے جس نے اس کے وقار، غیر جانب داری اور عوامی اعتماد کو گہری چوٹ پہنچائی ہے۔
گزشتہ برسوں میں ایسے فیصلے سامنے آئے جنہوں نے عوام میں عدلیہ کے بارے میں شکوک و شبہات کو بڑھا دیا ہے۔ جہاں ایک طرف سیاسی نوعیت کے مقدمات میں عدلیہ نے کبھی جلد بازی اور کبھی غیر ضروری تاخیر دکھائی، وہیں دوسری طرف آئینی طور پر اہم معاملات میں خاموشی یا مصلحت آمیز رویہ اختیار کیا گیا۔ مثال کے طور پر عام شہریوں کے فوجی ٹرائل کے خلاف درخواستیں یا چھبیسویں آئینی ترمیم کے حوالے سے دائر پٹیشنز — ان دونوں معاملات میں عدلیہ کا کردار غیر تسلی بخش رہا۔ ایک طرف آئین واضح ہدایات دیتا ہے کہ شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ سب سے پہلی ترجیح ہے، لیکن دوسری طرف عدلیہ کی خاموشی نے اس تاثر کو تقویت دی کہ شاید ادارہ جاتی دباؤ یا سیاسی مصلحتیں عدالتی عمل کو متاثر کر رہی ہیں۔
اس سے بڑھ کر یہ المیہ ہے کہ وہ جج صاحبان جو اپنے ادارے کی آزادی اور وقار کے دفاع کی کوشش کرتے ہیں، انہیں ذاتی اور پیشہ ورانہ سطح پر انتقام کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی مثال ہمارے سامنے ہے، جنہوں نے دیگر چار ججوں کے ہمراہ ایک خط کے ذریعے اعلیٰ عدلیہ کو حساس اداروں کی مبینہ مداخلت پر متوجہ کیا تھا۔ لیکن جلد ہی ان کے خلاف ایک پرانا تعلیمی تنازعہ دوبارہ زندہ کر دیا گیا اور ان کی قانون کی ڈگری منسوخ کر دی گئی۔ یہ اقدام محض ایک اتفاق نہیں بلکہ ایک واضح پیغام ہے کہ عدلیہ کے اندر سے اٹھنے والی مزاحمتی آوازوں کو دبانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جائے گا۔
سوال یہ ہے کہ جب ایک ہائی کورٹ کا جج اس طرح بدنام کیا جا سکتا ہے تو ایک عام شہری کیسے انصاف کی توقع رکھ سکتا ہے؟ اگر عدلیہ اپنے ہی ارکان کو تحفظ نہ دے سکے تو وہ عوامی حقوق کی کس طرح حفاظت کرے گی؟ یہی وہ نکتہ ہے جس نے عوام میں عدلیہ کے بارے میں شکوک کو شدید تر کر دیا ہے۔
پاکستان کے آئین میں عدلیہ کو سپریم حیثیت اس لیے دی گئی تھی کہ وہ طاقت کے توازن کو قائم رکھے، قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائے اور شہریوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرے۔ مگر جب عدلیہ اپنے ہی فیصلوں سے اس اصول کو مجروح کرے، تو پھر یہ خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ طاقتور طبقات اپنی مرضی کے قوانین بنا کر معاشرے کو اپنے مفاد کے مطابق چلائیں گے۔ ایسا معاشرہ بالآخر ایک “ہابسین اسٹیٹ” میں بدل جاتا ہے، جہاں طاقت ہی قانون بن جاتی ہے اور کمزور طبقے کو انصاف اور مساوات کا کوئی سہارا باقی نہیں رہتا۔
پاکستان میں عدلیہ کے حالیہ بحران کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے۔ سب سے پہلے یہ پہلو کہ عدلیہ سیاسی معاملات میں کیوں بار بار متنازع ہوتی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیاست اور ریاستی ادارے اکثر اپنے جھگڑوں کا حل عدالتوں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوں عدلیہ پر غیر معمولی دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن عدلیہ کا اصل امتحان یہی ہے کہ وہ اس دباؤ کے باوجود آئینی حدود کے اندر رہ کر فیصلہ کرے۔ بدقسمتی سے اکثر اوقات عدلیہ اس امتحان میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔
دوسرا پہلو یہ ہے کہ عدلیہ کے اندرونی اختلافات اور گروہ بندی نے اس کے وقار کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ حالیہ عرصے میں یہ منظر عام پر آیا کہ ایک ہی عدالت کے جج ایک دوسرے کے خلاف حکم جاری کر رہے ہیں، بعض ججوں کو ان کے اختیارات سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بعض کے فیصلوں کو دوسرے جج معطل کر رہے ہیں۔ اس صورت حال نے عدلیہ کو عوامی نظر میں مزید کمزور کر دیا ہے۔ ایک ادارہ جسے شفافیت اور اتحاد کی علامت ہونا چاہیے تھا، وہ خود اختلاف اور انتشار کا شکار ہے۔
تیسرا پہلو عوامی سطح پر عدلیہ کی ساکھ ہے۔ عام لوگ عدالتی فیصلوں کو اب انصاف کے بجائے طاقتوروں کے ایجنڈے کے مطابق سمجھنے لگے ہیں۔ جب کسی سیاست دان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو اس کے حامی اسے ’’انصاف کی توہین” کہتے ہیں، اور جب اسی سیاست دان کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو مخالفین اسے جوڈیشل انجینئرنگ” قرار دیتے ہیں۔ یہ کیفیت اس بات کی علامت ہے کہ عدلیہ نے اپنی غیر جانبداری کھو دی ہے، یا کم از کم عوام کو یہ یقین دلانے میں ناکام رہی ہے کہ اس کے فیصلے صرف آئین اور قانون کی بنیاد پر ہیں۔
اس صورت حال سے نکلنے کے لیے عدلیہ کو سب سے پہلے اپنے اندرونی نظام کو درست کرنا ہوگا۔ ججوں کی تقرری کے عمل کو شفاف بنانا ہوگا، تاکہ یہ تاثر ختم ہو کہ جج ذاتی یا ادارہ جاتی تعلقات کی بنیاد پر لائے جاتے ہیں۔ اسی طرح عدلیہ کو اپنے فیصلوں میں تاخیر کے بجائے بروقت انصاف فراہم کرنے کی روایت کو فروغ دینا ہوگا۔ انصاف میں تاخیر، انصاف کی نفی کے مترادف ہے۔
مزید برآں، عدلیہ کو اپنے فیصلوں میں آئین اور قانون کو مقدم رکھنا ہوگا، نہ کہ سیاسی یا ادارہ جاتی مصلحتوں کو۔ عوام کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ عدالتیں کسی طاقتور یا کمزور کے دباؤ میں نہیں آتیں بلکہ صرف آئین کی روشنی میں فیصلہ کرتی ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اعلیٰ عدلیہ اپنے اندر اتحاد پیدا کرے اور جج حضرات ایک دوسرے کے خلاف فیصلے دینے کے بجائے اجتماعی دانش اور مکالمے کے ذریعے مسائل حل کریں۔
اگر عدلیہ نے فوری طور پر اپنی اصلاح نہ کی تو اس کے نتائج انتہائی سنگین ہو سکتے ہیں۔ عوام کا اعتماد اگر ایک بار ٹوٹ جائے تو اسے بحال کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر طاقتور طبقات کو یقین ہو جائے کہ عدلیہ کمزور ہے اور وہ اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکتے ہیں، تو یہ رویہ پورے معاشرے کو قانون سے محروم کر دے گا۔
پاکستان کو ایک ایسے دوراہے پر کھڑا کیا جا رہا ہے جہاں یا تو عدلیہ اپنی آزادی، وقار اور غیر جانبداری کو بحال کرے گی، یا پھر تاریخ میں ایک ایسے ادارے کے طور پر یاد رکھی جائے گی جو اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کر گیا۔ عدلیہ کا کردار صرف فیصلے دینے تک محدود نہیں، بلکہ یہ اس قوم کے مستقبل کا تعین کرنے والا کردار ہے۔ اگر عدلیہ نے قانون کی حکمرانی کو مضبوط کیا تو پاکستان ایک مستحکم اور جمہوری ملک بن سکتا ہے، اور اگر عدلیہ نے یہ موقع گنوا دیا تو ملک ایک ایسے بحران میں داخل ہو سکتا ہے جس سے نکلنا آسان نہ ہوگا۔
لہٰذا وقت کی ضرورت یہ ہے کہ عدلیہ اپنے کردار کو پہچانے، اپنے فیصلوں کو آئینی بنیادوں پر استوار کرے، اندرونی اختلافات کو ختم کرے اور عوام کو یقین دلائے کہ عدالتیں ان کے بنیادی حقوق کی محافظ ہیں۔ اگر یہ اقدامات نہ کیے گئے تو نہ صرف عوام کا اعتماد ختم ہو جائے گا بلکہ عدلیہ اپنی ہی ساکھ اور وجود کے بحران کا شکار ہو جائے گی۔
عدلیہ کے بحران پر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں تاریخی تناظر کا جائزہ بھی لینا چاہیے، تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ آج کی صورت حال کیسے تشکیل پائی۔ پاکستان کی عدلیہ نے قیامِ پاکستان کے بعد سے ہی بارہا ایسے مواقع دیکھے جب وہ ملک کی سمت متعین کرنے میں مرکزی کردار ادا کر سکتی تھی۔ مگر اکثر اوقات عدلیہ نے اصولوں کے بجائے طاقتور قوتوں کے آگے جھکنے کو ترجیح دی۔ سب سے پہلی مثال 1954ء میں مولوی تمیز الدین کیس ہے، جب فیڈرل کورٹ نے گورنر جنرل کو اسمبلی توڑنے کا اختیار دے کر آئینی بحران کو جنم دیا۔ اسی طرح 1958ء میں مارشل لا کو قانونی جواز فراہم کرنے کے لیے نظریۂ ضرورت کا سہارا لیا گیا۔ یہ وہ موقع تھا جب عدلیہ آئین کے دفاع کے بجائے آمریت کے حق میں کھڑی نظر آئی۔
یہی رویہ بعد کے عشروں میں بھی دہراتا رہا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے مقدمے کو تاریخ اب تک ایک عدالتی قتل قرار دیتی ہے۔ جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف جیسے آمر بھی عدلیہ کے ہاتھوں ہی قانونی تحفظ پاتے رہے۔ جب قوم کو انصاف کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، عدلیہ نے یا تو خاموشی اختیار کی یا طاقتور کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اس پس منظر نے عدلیہ کو عوامی سطح پر ہمیشہ متنازع رکھا۔
تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ عدلیہ نے کچھ ایسے مواقع پر عوامی امنگوں کے مطابق فیصلے بھی دیے۔ چیف جسٹس افتخار محمد چوہدری کی بحالی تحریک نے عدلیہ کو عوامی طاقت کا احساس دلایا اور کچھ عرصے کے لیے عدلیہ نے فوجی آمریت کو چیلنج بھی کیا۔ لیکن جلد ہی عدلیہ نے اپنے اندرونی تضادات اور سیاسی اثرات کے زیرِ اثر رہ کر وہ ساکھ کھو دی جو بحالی تحریک کے دوران حاصل کی تھی۔
آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ جج حضرات خود ایک دوسرے پر بدعنوانی یا دباؤ کے الزامات لگا رہے ہیں، تو یہ عدلیہ کے ادارہ جاتی زوال کی واضح تصویر ہے۔ عوام کی نظر میں اب عدلیہ کسی “مقدس گائے” کی طرح نہیں بلکہ ایک ایسے ادارے کے طور پر دیکھی جاتی ہے جو خود بحرانوں کا شکار ہے۔
اس اداریہ میں یہ بات بھی اہم ہے کہ عدلیہ کے بحران کے اثرات محض عدالتوں تک محدود نہیں رہتے۔ جب انصاف مہنگا، تاخیر زدہ اور مشکوک ہو جائے تو عوام اپنے مسائل کے حل کے لیے غیر قانونی یا غیر رسمی راستوں پر چلنے لگتے ہیں۔ پنچایتیں، جرگے اور مقامی طاقتور افراد انصاف کے متبادل کے طور پر ابھرتے ہیں۔ یہ عمل نہ صرف آئین اور قانون کو کمزور کرتا ہے بلکہ معاشرے میں طاقتور اور کمزور کے درمیان فرق کو مزید بڑھا دیتا ہے۔
اسی تناظر میں ہمیں عدلیہ کی اصلاحات کی اشد ضرورت ہے۔ سب سے پہلی اصلاح ججوں کے احتساب کا شفاف اور غیر جانبدار نظام ہے۔ اگر کوئی جج بدعنوانی یا دباؤ کے تحت فیصلے کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن یہ کارروائی ادارہ جاتی انتقام یا سیاسی مصلحتوں سے بالاتر ہو۔ دوسری بڑی اصلاح عدالتی نظام کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے مؤثر اور تیز رفتار بنانا ہے۔ پاکستان کی عدالتوں میں لاکھوں مقدمات زیر التوا ہیں۔ جب ایک مقدمہ دہائیوں تک لٹکتا ہے تو انصاف کا تصور ہی برباد ہو جاتا ہے۔
عدلیہ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ عوامی اعتماد صرف آئینی موشگافیوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ عوام کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ان کا مقدمہ سننے والا جج آزاد ہے، غیر جانبدار ہے اور کسی ادارے یا فرد کے دباؤ میں نہیں۔ اگر یہ تاثر قائم ہو جائے تو عدلیہ دوبارہ عوام کا اعتماد حاصل کر سکتی ہے۔
یہاں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ عدلیہ کو اپنی آزادی کس طرح بحال کرنی چاہیے؟ اس کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ عدلیہ اپنے فیصلوں میں دوٹوک اور اصولی مؤقف اختیار کرے۔ اگر طاقتور ادارے عدلیہ پر دباؤ ڈالیں تو جج صاحبان کو اجتماعی طور پر اس دباؤ کو مسترد کرنا چاہیے۔ انفرادی سطح پر مزاحمت اکثر ناکام ہو جاتی ہے، لیکن اگر پورا ادارہ متحد ہو کر کھڑا ہو جائے تو کوئی قوت اسے زیر نہیں کر سکتی۔
عوام بھی عدلیہ کی آزادی کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جس طرح وکلا تحریک نے ایک وقت میں عدلیہ کو بحالی کی طاقت دی، اسی طرح آج بھی سول سوسائٹی، میڈیا اور وکلا کو چاہیے کہ عدلیہ کے اندر شفافیت اور آزادی کے مطالبے کو مضبوط کریں۔
پاکستان کی جمہوری بقا اور آئینی استحکام عدلیہ کے کردار پر منحصر ہے۔ اگر عدلیہ نے خود کو طاقتوروں کا آلہ کار بننے سے روکا اور آئین کی بالادستی کو یقینی بنایا تو یہ ملک ایک نئے دور میں داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر عدلیہ نے اپنے ہی بحران کو نظر انداز کیا تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔
آخر میں یہ کہنا لازم ہے کہ عدلیہ کا بحران صرف عدلیہ کا نہیں بلکہ پورے معاشرے کا بحران ہے۔ یہ بحران اگر حل نہ ہوا تو پاکستان میں انصاف کا چراغ مزید مدھم ہو جائے گا۔ وقت کی پکار یہی ہے کہ عدلیہ اپنی کھوئی ہوئی ساکھ واپس حاصل کرے، انصاف کو سستا اور بروقت بنائے اور عوام کو یہ یقین دلائے کہ عدالتیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں، نہ کہ طاقتوروں کے مفاد کے تابع۔