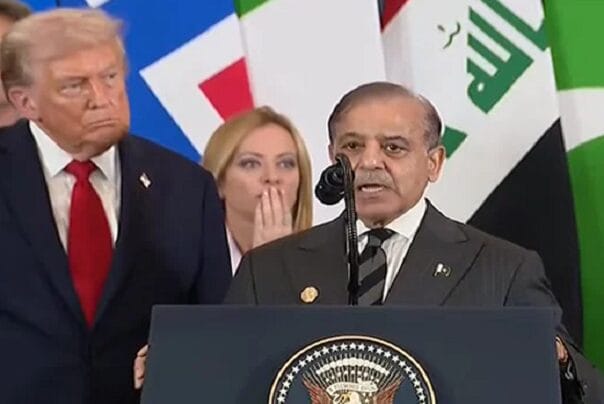پاک افغان سرحد پر جاری کشیدگی ایک بار پھر شدت اختیار کر چکی ہے۔ گزشتہ شب طورخم بارڈر پر فائرنگ کے تبادلے میں چھ سیکیورٹی اہلکار اور دو عام شہری زخمی ہوئے، جبکہ ایک شہری دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہو گیا۔ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں، بلکہ ایسے واقعات معمول بنتے جا رہے ہیں، جس کے اثرات دونوں ممالک کے عوام پر شدید پڑ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر اس تنازع کا حل کیا ہے؟ کیا محض مذاکرات ہی اس پیچیدہ مسئلے کو سلجھا سکتے ہیں؟
یہ حقیقت ہے کہ خیبرپختونخوا اور افغانستان کے عوام کے درمیان گہرے ثقافتی، لسانی اور خاندانی تعلقات ہیں۔ مگر دوسری طرف، دونوں ممالک کے درمیان سرحدی مسائل، دہشت گردی اور سیکیورٹی چیلنجز نے حالات کو مزید خراب کر دیا ہے۔ ہر بار جب سرحد پر کشیدگی بڑھتی ہے، عام شہری سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ وہ نہ صرف جان و مال کے نقصان سے دوچار ہوتے ہیں بلکہ نفسیاتی دباؤ کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔
طورخم بارڈر پر تازہ جھڑپ کے بعد مقامی افراد خوف و ہراس میں اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ رات کے اندھیرے میں لوگ بے سروسامانی کے عالم میں محفوظ مقامات کی تلاش میں بھاگے، کچھ برطانوی دور کے پرانے ریلوے سرنگوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ سرحدی کشیدگی کے باعث عام شہریوں کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، اور انہیں مسلسل غیر یقینی صورت حال کا سامنا ہے۔
دوسری طرف، افغان طالبان اور پاکستانی فورسز کے درمیان مذاکرات کی کوششیں مسلسل ناکام ہو رہی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات پہلے ہی تناؤ کا شکار ہیں، اور بارڈر کے مسائل مزید پیچیدگیاں پیدا کر رہے ہیں۔ افغان حکومت کا یہ مؤقف کہ وہ اپنی خودمختاری پر کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کرے گی، پاکستانی حکام کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے۔ اسی طرح، پاکستان کے لیے بھی اپنی سرحدوں کا دفاع اولین ترجیح ہے۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا دونوں ممالک کوئی درمیانی راستہ نکال سکتے ہیں؟
یہاں ایک اہم پہلو خیبرپختونخوا کی حکومت کی جانب سے افغان طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی خواہش بھی ہے۔ خیبرپختونخوا کے وزیراعلیٰ نے حالیہ ملاقات میں اس بات پر زور دیا کہ سرحدی مسائل کے حل کے لیے قبائلی جرگے کی مدد لی جائے گی، مگر اس کے لیے وفاقی حکومت کی منظوری ضروری ہوگی۔ اصولی طور پر یہ ایک قابل غور تجویز ہے، کیونکہ قبائلی عمائدین ماضی میں بھی کئی پیچیدہ مسائل کو پرامن طریقے سے حل کر چکے ہیں۔ لیکن کیا اس طرح کے مذاکرات قومی پالیسی سے متصادم تو نہیں ہوں گے؟
پاکستان میں تمام اہم سفارتی فیصلے وفاقی حکومت کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ اگر صوبے اپنی خارجہ پالیسی الگ سے مرتب کرنے لگیں تو یہ ملک کی مجموعی پالیسی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ خیبرپختونخوا کی حکومت اپنی تجاویز وفاقی سطح پر رکھے، تاکہ قومی سطح پر ایک متفقہ حکمت عملی ترتیب دی جا سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مذاکرات ہی کسی بھی تنازع کو حل کرنے کا بہترین طریقہ ہوتے ہیں، مگر یہ بھی ضروری ہے کہ ان مذاکرات کو قومی مفاد میں ترتیب دیا جائے۔
ایک اور اہم پہلو تجارت اور سرحدی آمد و رفت کا ہے۔ طورخم بارڈر گزشتہ کئی دنوں سے بند ہے، جس سے دونوں طرف تجارتی سرگرمیاں معطل ہو چکی ہیں۔ تاجر برادری شدید مشکلات کا شکار ہے اور عام شہری بھی روزمرہ کی اشیا کی قلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ افغان منڈیوں میں پاکستانی مصنوعات کی طلب ہمیشہ رہی ہے، اور سرحدی تجارت سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوتا ہے۔ بارڈر کی بندش نے نہ صرف تجارتی سرگرمیوں کو متاثر کیا ہے بلکہ روزگار پر بھی منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔
طورخم سرحد کی بندش سے سیکڑوں ٹرک لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں، جن میں خراب ہونے والی اشیا بھی شامل ہوتی ہیں۔ سبزی، پھل، گوشت اور دیگر ضروری اشیا کی رسد متاثر ہونے سے قیمتوں میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ یہ مسئلہ صرف افغانستان کے لیے نہیں، بلکہ پاکستان کے سرحدی علاقوں کے باشندوں کے لیے بھی پریشان کن ہے، کیونکہ ان کی روزی روٹی کا بڑا حصہ اسی تجارت پر منحصر ہے۔
اگر سفارتی سطح پر مسئلے کا حل نکالا جائے تو دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا۔ پاکستان اور افغانستان کی معیشتیں کسی نہ کسی حد تک ایک دوسرے پر انحصار کرتی ہیں، اور اگر بارڈر مستقل طور پر بند رہتا ہے تو اس کے معاشی اثرات مزید سنگین ہو سکتے ہیں۔
یہ وقت ہے کہ دونوں ممالک سرحدی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ جذباتی فیصلوں اور یک طرفہ اقدامات سے مسائل مزید بگڑ سکتے ہیں۔ پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ افغان حکام کے ساتھ ایک مستقل مذاکراتی پلیٹ فارم قائم کرے، جہاں دونوں ممالک کے تحفظات کو سنجیدگی سے سنا جا سکے اور ایک دیرپا حل تلاش کیا جا سکے۔ اسی طرح، افغان حکومت کو بھی یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ سرحدی کشیدگی کے خاتمے سے نہ صرف سیکیورٹی صورتحال بہتر ہوگی، بلکہ اس کے عوام کو بھی براہ راست فائدہ ہوگا۔
افغانستان کی موجودہ حکومت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ تصادم کسی کے بھی حق میں نہیں۔ اس کے برعکس، امن و استحکام دونوں ممالک کی ترقی کے لیے ناگزیر ہیں۔ اس مقصد کے لیے سفارت کاری کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان کسی غیر جانبدار ثالث کی موجودگی کو بھی یقینی بنایا جا سکتا ہے۔
آخر میں، ایک بار پھر یہ کہنا ضروری ہے کہ جنگ، تنازعات اور سرحدی جھڑپیں کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتیں۔ دونوں ممالک کو چاہیے کہ وہ اپنی ترجیحات کا ازسرنو جائزہ لیں اور سفارتی مذاکرات کے ذریعے دیرپا امن کی راہ ہموار کریں۔ قبائلی عمائدین، تاجر برادری اور عوام کے حقیقی مسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک متفقہ پالیسی ترتیب دی جائے، تاکہ خطے میں استحکام ممکن بنایا جا سکے۔ امن ہی وہ واحد راستہ ہے جو دونوں ممالک کے عوام کو ایک بہتر مستقبل کی طرف لے جا سکتا ہے۔
یہ بھی ضروری ہے کہ خیبرپختونخوا حکومت اپنی تجاویز وفاقی حکومت کے ساتھ شیئر کرے، تاکہ کوئی یکطرفہ اقدام قومی مفادات سے متصادم نہ ہو۔ پاکستان کو اپنی سفارت کاری کو مزید فعال بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ افغان حکام کو قائل کیا جا سکے کہ سرحدی کشیدگی کسی بھی فریق کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔
جب تک دونوں ممالک سنجیدہ مذاکرات اور مستقل پالیسی کے ذریعے تنازعات کا حل نہیں نکالتے، خطے میں کشیدگی برقرار رہے گی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ قیادتیں سنجیدہ اقدامات اٹھائیں، کیونکہ عوام اب مزید جنگ اور تصادم کے متحمل نہیں ہو سکتے۔
کپاس بحران، حل؟
پاکستان میں کپاس کی پیداوار مسلسل بحران کا شکار ہے، جو نہ صرف قومی معیشت بلکہ برآمدات، ٹیکسٹائل صنعت اور زراعت سے وابستہ لاکھوں افراد پر منفی اثرات مرتب کر رہی ہے۔ پاکستان کا شمار کبھی دنیا کے بڑے کپاس پیدا کرنے والے ممالک میں ہوتا تھا، مگر اب صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے۔ اس سال فروری کے آخر تک پاکستان میں کل کپاس کی پیداوار 5.524 ملین گانٹھیں ریکارڈ کی گئیں، جو گزشتہ سال کے 8.393 ملین گانٹھوں کے مقابلے میں 34.17 فیصد کمی ظاہر کرتی ہیں۔ یہ کمی نہ صرف زراعت بلکہ پوری صنعتی و برآمدی معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔
اس بحران کی کئی وجوہات ہیں جن میں موسمیاتی تبدیلی، کاشت کے رقبے میں کمی، پانی کی قلت، کھاد، بیج اور زرعی کیمیکلز کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور حکومتی پالیسیوں کی عدم موجودگی شامل ہیں۔ ان تمام عوامل نے کسانوں کو متبادل فصلوں کی طرف دھکیل دیا ہے، جس سے کپاس کا زیر کاشت رقبہ مزید کم ہو رہا ہے۔ پنجاب، جو پاکستان میں سب سے زیادہ کپاس پیدا کرتا تھا، اس سال سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ گزشتہ سال یہاں 4.778 ملین گانٹھ کپاس پیدا ہوئی تھی، جبکہ رواں سال یہ پیداوار کم ہو کر 2.477 ملین گانٹھ رہ گئی، یعنی 48.16 فیصد کمی دیکھنے میں آئی۔ سندھ میں بھی پیداوار میں کمی ہوئی ہے لیکن پنجاب کے مقابلے میں صورتحال کچھ بہتر ہے۔ سندھ میں کپاس کی پیداوار 3.614 ملین گانٹھوں سے کم ہو کر 3.046 ملین گانٹھوں تک آ گئی، جو 15.71 فیصد کی کمی ظاہر کرتی ہے۔ بلوچستان کی کپاس کی پیداوار میں کوئی خاص تبدیلی نہیں دیکھی گئی۔
پاکستان کی ٹیکسٹائل صنعت، جو ملکی برآمدات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس بحران سے شدید متاثر ہو رہی ہے۔ ٹیکسٹائل ملز کو خام مال کی قلت کا سامنا ہے، اور مقامی طور پر دستیاب کپاس کی کمی کی وجہ سے درآمدات میں اضافہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ تخمینے کے مطابق، رواں سال پاکستان کو تقریباً 5 ارب ڈالر مالیت کی کپاس درآمد کرنا پڑے گی، جس سے ملکی معیشت پر اضافی بوجھ پڑے گا۔
اس کے علاوہ، مقامی منڈی میں کپاس کے دام مسلسل گر رہے ہیں اور خرید و فروخت کی سرگرمیاں کم ہو رہی ہیں۔ کراچی کاٹن ایسوسی ایشن کے مطابق اس ہفتے مقامی مارکیٹ میں کپاس کی قیمتیں 16,500 سے 17,500 روپے فی من کے درمیان رہیں، جبکہ عالمی منڈی میں نیویارک کاٹن ایکسچینج پر قیمتیں 82 سینٹ فی پاؤنڈ کے لگ بھگ رہی ہیں۔
صورتحال کی سنگینی کے باوجود، حکومتی پالیسیوں میں سنجیدگی کی کمی نمایاں ہے۔ زرعی تحقیق اور جدید بیجوں کی فراہمی پر مناسب سرمایہ کاری نہ ہونے کے باعث کسان جدید ٹیکنالوجی سے محروم ہیں۔ اس کے علاوہ، سرکاری سطح پر کوئی مقررہ امدادی قیمت نہ ہونے کی وجہ سے کسان کپاس کی بجائے زیادہ منافع بخش فصلوں کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن مسلسل حکومت سے درخواست کر رہی ہے کہ مقامی کپاس کو مساوی سہولیات دی جائیں، مگر اب تک کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ اس کے برعکس، ٹیکسٹائل ملز کو سستی درآمدی کپاس فراہم کرنے کے لیے ٹیکس چھوٹ دی جا رہی ہے، جس سے مقامی کسانوں کو مزید نقصان پہنچ رہا ہے۔
پاکستان کے کپاس کے بحران سے نکلنے کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے تحقیق و ترقی میں سرمایہ کاری کی جائے تاکہ جدید بیجوں کی تیاری، کیڑے مار ادویات کے مؤثر استعمال اور موسمیاتی تبدیلیوں کے مطابق زراعت کے طریقوں کو بہتر بنایا جا سکے۔ پاکستان مرکزی کپاس کمیٹی اور پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل کو ضم کر کے ایک مشترکہ ادارہ بنایا جا سکتا ہے جو کپاس کی تحقیق پر خصوصی توجہ دے۔ حکومت کو کپاس کے لیے کم از کم امدادی قیمت کا اعلان کرنا ہوگا تاکہ کسانوں کو اس فصل کی طرف دوبارہ راغب کیا جا سکے۔ اس کے بغیر کپاس کے زیر کاشت رقبے میں مزید کمی کا خدشہ ہے۔ عالمی مارکیٹ میں پاکستانی کپاس کی طلب بڑھانے کے لیے برآمدی مراعات فراہم کی جائیں۔ برازیل جیسے ممالک سے تکنیکی تعاون حاصل کیا جا سکتا ہے جو کپاس کی پیداوار میں نمایاں بہتری لا چکے ہیں۔ کسانوں کو جدید مشینری، پانی کے بہتر استعمال کے طریقے، اور زرعی قرضوں میں نرمی فراہم کی جائے تاکہ وہ کپاس کی پیداوار میں اضافہ کر سکیں۔ مقامی کسانوں کے مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے درآمدی کپاس پر ٹیکس میں نظرثانی کی جائے تاکہ مقامی پیداوار کو تحفظ دیا جا سکے۔
پاکستان کی معیشت اور ٹیکسٹائل صنعت کا دار و مدار بڑی حد تک کپاس پر ہے، اور اگر اس بحران پر فوری قابو نہ پایا گیا تو اس کے منفی اثرات پورے ملک پر مرتب ہوں گے۔ کسان، صنعتکار اور برآمد کنندگان سب ہی اس صورتحال سے متاثر ہو رہے ہیں، اور اگر حکومت نے اس مسئلے پر توجہ نہ دی تو آئندہ برسوں میں کپاس کی پیداوار مزید کم ہو سکتی ہے، جس سے درآمدی بوجھ میں اضافہ ہوگا اور ملکی معیشت مزید مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ یہ وقت ہے کہ حکومت اور پالیسی ساز کپاس کے شعبے کی بحالی کے لیے عملی اقدامات کریں تاکہ کسانوں کو دوبارہ اس فصل کی طرف متوجہ کیا جا سکے، صنعتوں کو خام مال کی مناسب فراہمی یقینی بنائی جا سکے، اور پاکستان عالمی مارکیٹ میں دوبارہ کپاس کے ایک اہم برآمد کنندہ کے طور پر ابھر سکے۔ اگر آج اس مسئلے کو نظر انداز کیا گیا تو مستقبل میں اس کے نتائج نہایت سنگین ہوں گے۔
ڈیجیٹل معیشت، راستہ؟
پاکستان میں ڈیجیٹل اثاثے ابھر رہے ہیں اور معیشت میں ان کا کردار بڑھتا جا رہا ہے۔ عالمی سطح پر ان اثاثوں کی اہمیت کو تسلیم کیا جا چکا ہے، اور کئی ممالک نے ان کے لیے واضح پالیسیاں ترتیب دی ہیں۔ پاکستان میں بھی ڈیجیٹل معیشت کو فروغ دینے کی کوششیں جاری ہیں، لیکن اب تک کوئی جامع حکمت عملی سامنے نہیں آ سکی۔ یہ صورتحال مستقبل کے مالیاتی نظام میں پاکستان کی شمولیت پر سوالیہ نشان لگا سکتی ہے۔
حالیہ دنوں میں حکومت نے کرپٹو کرنسی اور دیگر ڈیجیٹل اثاثوں کے حوالے سے پالیسی ترتیب دینے کے ارادے ظاہر کیے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ نے ایک قومی کرپٹو کونسل کے قیام کا عندیہ دیا ہے، جس کا مقصد ڈیجیٹل معیشت کو بہتر طریقے سے منظم کرنا ہوگا۔ تاہم، اس معاملے کو صرف کرپٹو کرنسی تک محدود رکھنا دانشمندانہ نہیں ہوگا، بلکہ پورے ویب تھری فریم ورک کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک جامع پالیسی تشکیل دینا ہوگی۔ دنیا تیزی سے ڈیجیٹل معیشت کی طرف بڑھ رہی ہے، اور پاکستان کو بھی اس تبدیلی کے لیے تیار رہنا ہوگا۔
اسٹیٹ بینک آف پاکستان اب بھی کرپٹو کرنسی کو شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈیجیٹل معیشت اب ایک حقیقت بن چکی ہے۔ کرپٹو کرنسی کے ساتھ ساتھ نان فنجیبل ٹوکن اور بلاک چین ٹیکنالوجی جیسے جدید تصورات بھی سامنے آ چکے ہیں، جن کی معیشت میں وسیع پیمانے پر ایپلی کیشنز موجود ہیں۔ اگر پاکستان ان شعبوں میں پیچھے رہ گیا تو مستقبل کی معیشت میں اس کا حصہ محدود ہو جائے گا۔
مکمل طور پر کرپٹو کرنسی کو مسترد کرنا ممکن نہیں، لیکن اسے غیر محدود رسائی دینا بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان کو ان اثاثوں کو ایک منظم دائرے میں لانے کے لیے پالیسی ترتیب دینی چاہیے۔ دنیا کے کئی ممالک نے کرپٹو کرنسی کے لیے واضح قوانین متعارف کرائے ہیں، جن میں متحدہ عرب امارات کا ماڈل خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ پاکستان کو بھی اسی ماڈل کو اپنانا ہوگا، تاکہ ایک مستحکم ڈیجیٹل اثاثہ مارکیٹ قائم کی جا سکے جو معیشت کو فائدہ پہنچائے۔
بلاک چین ٹیکنالوجی نہ صرف کرپٹو کرنسی کی تجارت کے لیے اہم ہے، بلکہ اس کے فوائد دیگر شعبوں میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کو جائیداد کی خرید و فروخت، ڈیجیٹل آرٹ، آٹو موبائل ٹرانزیکشنز، اور دیگر مالیاتی اثاثوں کے لین دین میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ بلاک چین کا ریکارڈ ناقابلِ تغیر ہوتا ہے، جس سے دھوکہ دہی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے کئی بڑے ادارے بلاک چین کو اپنے کاروباری ماڈلز میں ضم کر رہے ہیں، اور پاکستان کو بھی اس نئی معیشتی حقیقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔
ماضی میں حکومت اور مرکزی بینک ڈیجیٹل اثاثوں کے حوالے سے محتاط رویہ اختیار کرتے رہے ہیں، لیکن اب وزیر خزانہ اس معاملے پر کھلی نظر رکھتے ہیں۔ یہ ایک مثبت پیش رفت ہے جو پاکستان کو عالمی ڈیجیٹل مالیاتی نظام میں شامل ہونے کا موقع دے سکتی ہے۔ تاہم، اگر اس معاملے کو سنجیدگی سے نہ لیا گیا تو پاکستان ڈیجیٹل معیشت کی دوڑ میں مزید پیچھے رہ جائے گا۔
اسٹیٹ بینک کو اپنی پالیسی میں نرمی لاتے ہوئے ڈیجیٹل لین دین کو قانونی شکل دینے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اگر ایک جامع ویب تھری فریم ورک ترتیب دیا جائے تو یہ ملک میں مالیاتی لین دین کو مزید محفوظ اور مؤثر بنا سکتا ہے۔ اس کے ذریعے ترسیلات زر کے اخراجات کم کیے جا سکتے ہیں، جس سے بینکنگ چینلز زیادہ پرکشش بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، کراؤڈ فنڈنگ اور جائیداد کی ٹوکنائزیشن جیسے تصورات بھی ممکن ہو سکتے ہیں، جو ملکی معیشت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔
یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں لاکھوں افراد پہلے ہی کرپٹو کرنسی اور دیگر ڈیجیٹل اثاثوں میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ تاہم، ان کے لیے کوئی واضح قانونی تحفظ موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ مختلف مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ حکومت کو اس شعبے کو ضابطے میں لا کر ایک ایسا ماحول بنانا ہوگا، جہاں سرمایہ کار محفوظ طریقے سے ڈیجیٹل اثاثوں میں سرمایہ لگا سکیں۔
کرپٹو کرنسی کے خلاف ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ یہ غیر قانونی سرگرمیوں میں استعمال ہو سکتی ہے۔ ڈارک ویب پر زیادہ تر مالیاتی لین دین کرپٹو کرنسی کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور اس کا استعمال منشیات فروشوں، دہشت گردوں اور دیگر جرائم پیشہ افراد کے ہاتھوں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر پاکستان میں بغیر کسی ضابطے کے کرپٹو کرنسی کی اجازت دے دی گئی تو یہ فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کے ضوابط کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے، جو ملک کے لیے مزید مالی مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔
اس کے باوجود، مکمل پابندی کوئی حل نہیں ہے۔ دنیا کے کئی ممالک نے کرپٹو کرنسی اور دیگر ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے جامع پالیسی مرتب کی ہے۔ پاکستان کو بھی اس ماڈل کو اپنانا ہوگا اور مقامی ضروریات کے مطابق قانون سازی کرنی ہوگی۔ متحدہ عرب امارات اس حوالے سے ایک کامیاب مثال ہے، جہاں کرپٹو کرنسی کو قانونی شکل دے کر اسے ضابطے میں لایا گیا ہے۔ اگر پاکستان بھی ایسا کرے تو اس سے ملکی معیشت کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، جبکہ غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔
ڈیجیٹل اثاثے صرف کرپٹو کرنسی تک محدود نہیں ہیں۔ نان فنجیبل ٹوکن اور دیگر ڈیجیٹل اثاثے بھی عالمی معیشت کا حصہ بن رہے ہیں۔ چند سال قبل ایک پاکستانی وائرل میم “مدثر دوستی ختم” کو آن لائن نیلامی میں 20 ایتھریم ٹوکن میں فروخت کیا گیا تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈیجیٹل اثاثوں کی تجارت میں بڑا پوٹینشل موجود ہے۔ تاہم، یہ شعبہ ابھی تک غیر منظم ہے، اور اس کی ترقی کے لیے ایک واضح پالیسی کی ضرورت ہے۔
اس وقت پاکستان میں ڈیجیٹل اثاثوں کی پالیسی تشکیل دینے کے لیے کوئی ایک مرکزی ادارہ نہیں ہے، جو اس معاملے کو الجھا رہا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس کام کے لیے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کو مقرر کرے اور ایک جامع حکمت عملی بنائی جائے، جو نہ صرف سرمایہ کاروں کے تحفظ کو یقینی بنائے بلکہ ملکی معیشت کو بھی مستحکم کرے۔
ڈیجیٹل اثاثوں کے فروغ کے لیے قانون سازی انتہائی ضروری ہے۔ جب تک اس حوالے سے واضح قوانین نہیں بنائے جاتے، پاکستان میں اس شعبے کی ترقی ممکن نہیں ہو سکتی۔ انگلینڈ میں قانون کمیشن نے ڈیجیٹل اثاثوں کو تسلیم کرنے اور انہیں قانونی تحفظ دینے کے لیے کام شروع کر دیا ہے۔ پاکستان کو بھی اس طرز کا ایک قانونی ڈھانچہ تشکیل دینا ہوگا تاکہ شہری ان اثاثوں کو محفوظ طریقے سے خرید و فروخت کر سکیں۔
پاکستان میں ڈیجیٹل اثاثوں کی ترقی کے کئی امکانات موجود ہیں۔ ٹیلی کام انڈسٹری میں موبائل بیلنس کی خرید و فروخت، کریڈٹ کارڈ پوائنٹس کی ٹریڈنگ، اور ڈیجیٹل آرٹ مارکیٹ کو منظم کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان شعبوں کو باضابطہ شکل دی جائے تو یہ ملکی معیشت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت ایک واضح پالیسی ترتیب دے اور متعلقہ اداروں کو متحرک کرے۔
ڈیجیٹل معیشت کی ترقی کے لیے حکومت کو ٹیکنالوجی اور پالیسی سازی کو یکجا کرنا ہوگا۔ پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ کی ڈیجیٹلائزیشن بھی پالیسی اقدامات کے نتیجے میں ممکن ہوئی تھی۔ اگر حکومت اس ماڈل کو ڈیجیٹل اثاثوں پر بھی لاگو کرے تو یہ شعبہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ یہ وقت ہے کہ حکومت ڈیجیٹل اثاثوں کو اپنانے کے لیے عملی اقدامات کرے، تاکہ پاکستان اس عالمی معاشی تبدیلی کا حصہ بن سکے۔