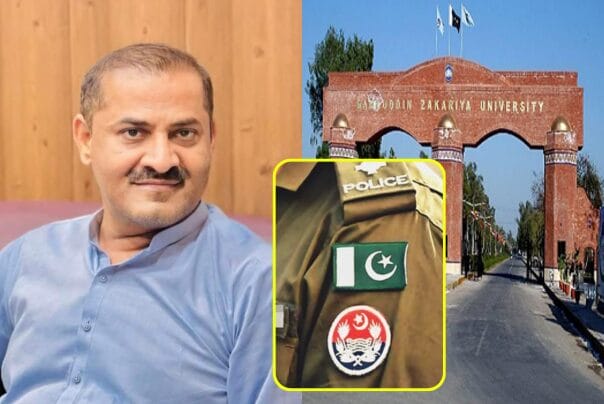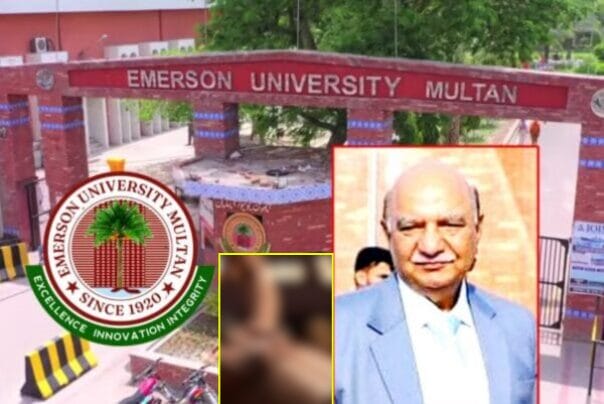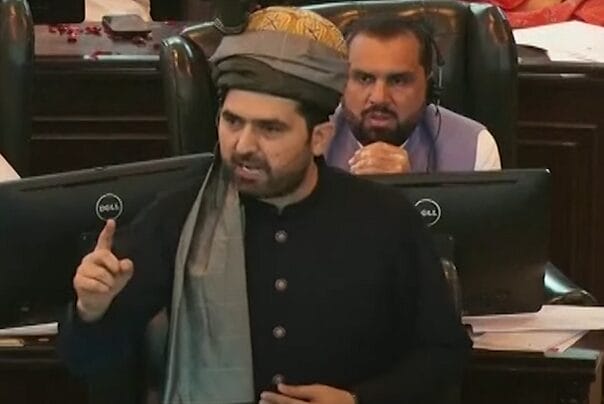پاکستان کی سیاسی فضاؤں میں ایک بار پھر آئینی ترمیم کا چرچا ہے۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ (ن) کے حلقوں میں 1973ء کے آئین میں 27ویں آئینی ترمیم کا ایک خاکہ زیرِ بحث ہے۔ اگرچہ ابھی اس مسودے کی تفصیلات منظرِ عام پر نہیں آئیں، مگر سیاسی اور قانونی حلقوں میں یہ قیاس آرائیاں زور پکڑ رہی ہیں کہ اس ترمیم کا مقصد عدلیہ میں مزید اصلاحات متعارف کرانا اور این ایف سی ایوارڈ کے نفاذ کے ڈھانچے میں تبدیلی کرنا ہے۔ یہ دونوں نکات بظاہر انتظامی اور مالیاتی کارکردگی کو بہتر بنانے کی نیت سے وابستہ ہیں، مگر پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ نیت اور نتیجہ اکثر ایک دوسرے کے برعکس نکلتے ہیں۔عدلیہ میں اصلاحات کا جواز پیش کرنے والے کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے باوجود عدالتی ڈھانچے میں وہ تبدیلیاں نہیں ہو سکیں جن کی حکومت خواہش مند تھی۔ اسی طرح این ایف سی ایوارڈ کے بارے میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس کے موجودہ نفاذ سے وفاق اور صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم میں عدم توازن پیدا ہو رہا ہے، جسے ایک نئی ترمیم کے ذریعے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر اپوزیشن جماعتوں، آزاد قانونی ماہرین اور آئینی ماہرین کا موقف ہے کہ یہ سب کچھ ایک وسیع تر سیاسی منصوبے کا حصہ ہے، جس میں ریاستی اداروں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ ترمیم واقعی عوامی مفاد میں ہوگی یا یہ ایک اور اقدام ہوگا جو اقتدار کے کھیل میں طاقت کے پلڑے کو ایک جانب جھکا دے گا؟اس تنقید میں ایک گہری تاریخی تلخی شامل ہے، کیونکہ پاکستان کا آئینی سفر 1973ء سے لے کر آج تک ایک سیدھی لکیر میں نہیں بلکہ پیچیدہ موڑ اور خطرناک ڈھلوانوں سے گزرتا آیا ہے۔ 1973ء میں متفقہ آئین کا نفاذ بلاشبہ پاکستان کی تاریخ کا ایک روشن لمحہ تھا۔ اس آئین نے نہ صرف وفاقی پارلیمانی نظام کی بنیاد رکھی بلکہ شہری آزادیوں، صوبائی خودمختاری اور ریاستی اداروں کے دائرہ کار کو واضح کیا۔ لیکن اس خوش کن آغاز کے فوراً بعد اقتدار کی سیاست نے آئین کو اپنے مقاصد کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا۔جنرل ضیاء الحق کے دور میں متعارف کرائی جانے والی 8ویں آئینی ترمیم اس عمل کی ایک بڑی مثال ہے۔ اس ترمیم نے صدر کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اختیار دے کر پاکستان کے پارلیمانی نظام کی جڑوں میں ایک مستقل دراڑ ڈال دی۔ یہ ترمیم وقتی ضرورت یا “نظام بچانے” کے نام پر لائی گئی تھی، مگر اس نے عوامی مینڈیٹ کو کمزور کر کے اقتدار کو فرد واحد کے ہاتھ میں مرکوز کر دیا۔ بعد میں آنے والی 17ویں آئینی ترمیم، جو جنرل پرویز مشرف کے دور میں لائی گئی، بھی اسی سوچ کا تسلسل تھی۔جمہوری ادوار میں بھی آئین کے ساتھ سلوک مختلف نہ رہا۔ 1990ء کی دہائی میں آنے والی مختلف ترامیم کا مقصد اکثر سیاسی مخالفین کو کچلنا، عدلیہ یا احتسابی اداروں کو اپنے قابو میں رکھنا، یا حکومت کی آئینی مدت کو غیر یقینی بنانا رہا۔ یوں آئین، جو قوم کا اجتماعی معاہدہ تھا، وقتاً فوقتاً طاقت ور حلقوں کے ہاتھوں میں ایک لچک دار آلہ بنتا گیا۔ان ترامیم کا سب سے خطرناک اثر یہ ہوا کہ ریاست کا آئینی، قانونی، انتظامی اور عدالتی ڈھانچہ اپنی اصل روح سے دور ہوتا گیا۔ اداروں کی کارکردگی زوال پذیر ہوئی کیونکہ ان کی ساخت کو بار بار وقتی سیاسی مفادات کے مطابق بدلا گیا۔ عدلیہ پر اثرانداز ہونے کی کوششوں نے انصاف کے تصور کو متنازع بنایا، اور بیوروکریسی کو سیاسی دباؤ کے آگے جھکنے پر مجبور کیا۔ این ایف سی ایوارڈ جیسے مالیاتی معاہدے بھی اسی کھینچا تانی کا شکار ہوئے، جن کا مقصد صوبوں کے حقوق کو محفوظ بنانا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان پر بھی مرکز اور صوبوں کے درمیان عدم اعتماد کا سایہ پڑ گیا۔آج جب 27ویں آئینی ترمیم کا ذکر ہوتا ہے تو یہ محض ایک قانونی معاملہ نہیں بلکہ پاکستان کی آئینی تاریخ کی تلخ یادوں کو تازہ کرتا ہے۔ اگر اس ترمیم کا مقصد واقعی عدلیہ میں اصلاحات اور این ایف سی کے بوجھ کو متوازن کرنا ہے تو اس کے لیے شفافیت اور مشاورت لازم ہے۔ مگر اگر یہ ترمیم بھی گزشتہ ترامیم کی طرح طاقت کے توازن کو ایک جانب جھکانے کا ہتھیار بنی، تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو ماضی میں ہوا: وقتی فائدہ، مگر دیرپا نقصان۔طاقت اور اختیار کی فطرت یہ ہے کہ یہ کبھی ایک جگہ نہیں ٹھہرتے۔ آج جو جماعت یا فرد خود کو ناقابلِ چیلنج سمجھتا ہے، کل کو اسی آئینی ڈھانچے کا قیدی بن سکتا ہے جسے اس نے اپنی مرضی سے تراشا ہو۔ تاریخ کے صفحات بھٹکنے والے حکمرانوں سے بھرے پڑے ہیں جنہوں نے اپنے لیے مضبوط قلعے تعمیر کیے، مگر وقت کی ہوا نے ان قلعوں کو ریت کے ذروں میں بدل دیا۔پاکستان کا آئین قوم کا اجتماعی عہد ہے، نہ کہ کسی ایک دورِ حکومت کا ذاتی منشور۔ ہر ترمیم جو آئین کی بنیادی روح کو کمزور کرے گی، وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک نیا بوجھ بنے گی۔ اس لیے حکمرانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حقیقت کو سمجھیں کہ عوامی اعتماد اور آئینی بالادستی طاقت کا سب سے مضبوط سرچشمہ ہیں، نہ کہ وقتی اکثریت یا پارلیمانی چالاکیاں۔اگر آج اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے لوگ یہ سمجھ لیں کہ آئین کے ساتھ کھیلنا دراصل اپنی ہی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا ہے، تو شاید آنے والے دنوں میں ہم ایک ایسے پاکستان کے گواہ بن سکیں جہاں آئین کو صرف اس وقت بدلا جائے جب اس کی ضرورت پوری قوم محسوس کرے، نہ کہ چند طاقت ور حلقے۔ ورنہ “میری تعمیر میں مضمر ہے اک صورت خرابی کی” کا یہ مصرع محض شاعری نہیں، ہماری آئینی تاریخ کا مستقل عنوان بن جائے گا۔پاکستان کی سیاست کے اس پیچیدہ موڑ پر سوال یہ نہیں کہ 27ویں ترمیم آئے گی یا نہیں؛ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہماری جمہوریت پسندی کے بلند آہنگ دعوے اقتدار کے دروازے کھلتے ہی ہر بار اسی پرانی روش کو جنم دیتے رہیں گے—آئین کے خدوخال بگاڑنا، شہری و جمہوری آزادیوں کو روندنا، صحافت کو پابندِ سلاسل کرنا، جیلوں کو سیاسی مخالفین سے بھرنا اور عدالتوں کو سیاست کے میدان میں ریفری کے بجائے ایک فریق میں بدل دینا؟ تاریخ کے تجربات دل خوش کن جواب نہیں دیتے۔ جب بھی سیاسی اقتدار میسر آتا ہے، ہمارے اکثر لیڈر “اصلاحات” کے نام پر وہی پرانے نسخے آزماتے ہیں جن کی وہ کل تک مذمت کرتے تھے۔ کل تک جو قانون آمرانہ کہلاتا تھا، آج “ریاستی ضرورت” بن جاتا ہے؛ جو اختیار کل “غیرمنتخب طاقت” کا ناجائز ہتھیار تھا، آج “جمہوری استحکام” کی ضمانت ٹھہرتا ہے۔ یہ منافقت محض اخلاقی کمزوری نہیں، حکمرانی کی ناکامی کا بنیادی سبب بھی ہے۔یہ حقیقت بھی ڈھکی چھپی نہیں کہ ہماری غیر منتخب ہئیتِ مقتدرہ اور اس کے انتظامی اداروں میں وہی پرانی سرپرستی اور طالع آزمائی کی روایت پلتی رہی ہے جس نے ہر دور میں بالقوہ آمریت کو بالادستی کی راہ دی۔ سیاسی اشرافیہ اقتدار سے باہر ہو تو “بالادست مداخلت” کے خلاف جھنڈا اٹھاتی ہے، اقتدار میں آئے تو اسی ڈھانچے کی سہولتوں سے فائدہ اٹھاتی ہے—کبھی فائلوں کی رفتار سے، کبھی قانون کے اطلاق سے، کبھی “سلامتی” کے مبہم جواز سے۔ سوال یہ ہے کہ یہ باہمی گٹھ جوڑ کب ٹوٹے گا؟ اور اگر ٹوٹے گا تو کیسے؟ محض بیانیہ بدلنے سے نہیں، طریقِ حکمرانی بدلنے سے۔ جب تک سیاسی قوتیں پارلیمان، کابینہ، قائمہ کمیٹیوں، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو حقیقی طاقت دے کر فیصلوں کو ادارہ جاتی نہیں بناتیں، اقتدار خواہ سیاسی جماعت کے ہاتھ میں ہو یا کسی اور کے، “مرکزِ اختیار” دراصل کمرۂ عدالت، کسی دفتر کی میز یا بند کمرے کی مشاورت میں منتقل رہے گا—وہیں جہاں جوابدہی کم اور صوابدید زیادہ ہوتی ہے۔جمہوری و شہری آزادیوں کی پامالی ہمارے ہاں ہمیشہ “استثنائی حالات” کے نام پر ہوتی رہی ہے—کبھی امن و امان، کبھی دہشت گردی، کبھی معاشی ایمرجنسی، کبھی “جھوٹی خبر” کے تعاقب میں۔ مگر استثنا جب معمول بن جائے تو قانون “Rule of Law” نہیں رہتا، “Rule by Law” بن جاتا ہے—یعنی قانون انصاف کے لیے نہیں، اختیار کے لیے ڈھال۔ صحافت کی زبان بندی، ڈیجیٹل ضابطہ بندی کی مبہم شقیں، ہتکِ عزت اور غداری جیسے قدیم کالونیل ہتھیاروں کا بے محابا استعمال، یہ سب اس بات کی علامت ہیں کہ حکمران طبقہ فوری سیاسی فائدے کے لیے طویل المدت نقصان مول لے لیتا ہے۔ ہر دور میں کچھ صحافی “طاقت پرستی” کے نام پر ٹھکانے لگتے ہیں، کچھ صحافتی ادارے “مالیاتی قواعد” کے نام پر دباؤ میں آتے ہیں، کچھ آوازیں “قومی مفاد” کے بوجھ سے خاموش کرا دی جاتی ہیں—اور یوں سماج میں خوف اور خود سنسوری کا زہر اترتا چلا جاتا ہے۔عدالتوں کو سیاسی بساط پر مہرہ بنانے کی روایت بھی بدیسی نہیں، مقامی ایجاد ہے۔ کبھی ازخود نوٹس کے بے ہنگم استعمال سے، کبھی بنچ فکسنگ کی کاناپھوسیوں سے، کبھی انتخابی تنازعات کے قضیے کو قانونی بجائے سیاسی مکالمے سے حل کرنے کے بجائے کٹہروں میں گھسیٹنے سے۔ یوں عدلیہ، جسے آئینی تنازعات کی آخری غیرجانبدار عدالت ہونا چاہیے، سیاسی انجینئرنگ کے گرداب میں کھنچتی چلی جاتی ہے۔ سیاسی قوتیں جب عدالتوں کو اپنے مخالفین کی گرفت کے لیے ڈھال بناتی ہیں تو یہ بھول جاتی ہیں کہ کل کو یہی تلوار ان کے اپنے سَر پر لٹک سکتی ہے۔ “نظریۂ ضرورت” صرف ایک تاریخی عبارت نہیں، ایک ذہنیت ہے—اور وہ ذہنیت تب تک زندہ رہتی ہے جب تک سیاستدان اسے اپنے سہولت کار کے طور پر قبول کرتے رہیں۔اب سوالات کے سیدھے جواب۔ کیا ہماری سیاسی اشرافیہ اس روش سے باز آئے گی؟ تب ہی جب اسے سمجھ آ جائے کہ اقتدار میں آکر “اصلاحات” کا مطلب اختیارات کی مرکزیت نہیں، ان کی تقسیم ہے۔ اصلاحات وہ جو طاقت کو بکھیرتی ہیں: مضبوط مقامی حکومتیں جن کے مالی و انتظامی اختیارات آئین میں ضمانت یافتہ ہوں؛ پارلیمانی نگرانی جس کے سامنے کابینہ و سیکورٹی ادارے جواب دہ ہوں؛ عدالتی اصلاحات جو شفاف تقرری، بنچ تشکیل کے اصول، مقدمات کی ترجیح اور جوابدہی کو قواعد میں باندھ دیں؛ میڈیا کے لیے واضح، محدود اور حقوق پسند ضابطے جن میں گرفتاری آخری حربہ ہو اور اظہارِ رائے کا حق اولین قدر۔ اگر “اصلاح” کے نام پر نئے اختیار تراشے جا رہے ہوں، نئے جرم ایجاد کیے جا رہے ہوں، یا اختلافِ رائے کو جرم بنا دیا جا رہا ہو تو سمجھ لیجیے ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں کل تھے—بس کردار بدل گئے ہیں، کہانی نہیں۔یہ سیاسی طبقہ غیر منتخب قوتوں کی نرسری میں پیدا ہونے والے “بالقوہ آمروں” کی پرورش روکنا کب سیکھے گا؟ جب سیاسی جماعتیں “منتخب ہونے” کے ساتھ “منتخب رکھنے” کی اہل ہو جائیں۔ اس کا پہلا زینہ اندرونی جمہوریت ہے—شفاف رکنیت، حقیقی جماعتی انتخابات، پالیسی پر داخلی مناظرے، فنڈنگ کا حساب۔ دوسرا زینہ انتخابی عمل کی ساکھ ہے—قبل از انتخاب انجینئرنگ کی حوصلہ شکنی، امیدواروں کی وفاداریوں کی بندربانٹ سے انکار، نتائج کی تیاری و ترسیل میں شفاف ٹیکنالوجی اور قانون کی پابندی، اور سب سے بڑھ کر شکست تسلیم کرنے کا سیاسی حوصلہ۔ تیسرا زینہ پارلیمان کی باوقاری ہے—قانون سازی جلدی میں نہیں، کمیٹیوں کی کڑی جانچ کے بعد؛ صدارتی آرڈیننسز کے ہتھوڑے کی جگہ کھلی بحث؛ بجٹ اور این ایف سی جیسے کٹھن فیصلوں میں بین الصوبائی اعتماد سازی اور کھلے اعدادوشمار۔ جب سیاست “معاہدۂ اصول” پر استوار ہو، تبھی غیر منتخب طاقتوں کے لیے خلا کم رہ جاتا ہے۔ووٹ کی پرچی کا احترام کب سیکھا جائے گا؟ جب ہر سیاسی جماعت یہ عہد کرے کہ اقتدار میں آ کر انتخابی قوانین اپنی سہولت کے لیے نہیں بدلے گی؛ الیکشن کمیشن کو علاقائی/قومی ہیئت مقتدرہ سے آزاد اور پارلیمان کے سامنے جواب دہ ادارہ بنائے گی؛ انتخابی تنازعات کو 90 دن کے اندر نمٹانے کے لیے خصوصی عدالتیں اور واضح ٹائم لائنز مقرر کرے گی؛ اور ریاستی وسائل کے انتخابی استعمال کو سنگین جرم قرار دے گی۔ ووٹ کا تقدس صرف نتیجے کے دن نہیں ہوتا؛ یہ پانچ سال تک ہر اس فیصلے میں اپنی شکل دکھاتا ہے جس میں عوام کو اعتماد میں لیا جائے، معلومات شیئر کی جائیں، اور اختلاف کرنے والوں کو غدار یا فتنہ گر کہہ کر باہر نہ دھکیلا جائے۔کیا یہ سیاسی قوتیں اقتدار میں آ کر وہی جمہوری مثالیہ برقرار رکھیں گی جو حزبِ اختلاف میں اپناتی ہیں؟ یہ تبھی ممکن ہے جب سیاسی اخلاقیات کو ادارہ جاتی بنایا جائے—مفادات کے ٹکراؤ کے سخت قوانین، وزرائے اعظم/وزراء کے اثاثہ جات کی مستقل عوامی ڈکلیئریشن اور آڈٹ، پبلک پروکیورمنٹ کے فولادی قواعد، لابنگ اور سیاسی فنڈنگ کی شفاف رجسٹری، اور سب سے بڑھ کر پارلیمانی اخلاقی کمیٹیوں کے بے لاگ اختیارات۔ جب اصولوں کی قیمت فوری سیاسی فائدے سے زیادہ ہو جائے—اور اس قیمت کی ادائیگی یقینی ہو—تبھی “حکومت” اور “حکمرانی” میں فرق واضح ہوگا۔حقیقت یہ ہے کہ عوام کا صبر لبریز ہو چکا ہے۔ جب عدالتیں سیاست کے گتھم گتھا تنازعات میں الجھی ہوں، جب میڈیا میں خبر سے زیادہ خوف گردش کرے، جب پولیس و انتظامیہ قانون سے زیادہ اشارے دیکھتی ہو، جب پارلیمان میں قانون سازی مباحثے کے بجائے تختہ مشق بن جائے، تو عام آدمی کے لیے آئین، قانون، جمہوریت اور آزاد صحافت سب مذاق محسوس ہونے لگتے ہیں۔ یہ صرف سیاسی یا آئینی بحران نہیں، اخلاقی بحران ہے—وہ لمحہ جب سماج یہ مان بیٹھے کہ انصاف میسر نہیں، صرف حیثیت میسر ہے؛ قانون برحق نہیں، برائے کار ہے۔ ایسے میں ریاستیں خالی خانوں میں نہیں ٹھہرتیں؛ خلا کو شور، افواہ، سازش، انتقام اور آخرکار بےنظمی—انارکی—بھرتی ہے۔اس دہانے سے پیچھے ہٹنے کا راستہ موجود ہے، مگر اس کے لیے قیمت ہے: طاقت کی تقسیم، صوابدید کی تحدید، اور شفافیت کی تکلیف دہ روشنی۔ سیاسی اشرافیہ کو خود اپنا احتساب کرنا ہوگا—صرف مخالفین کا نہیں۔ظالمانہ قوانین کی منسوخی، کالونیل دور کی غداری و بغاوت جیسی مبہم دفعات کی تطہیر، ڈیجیٹل اظہار پر متوازن اور حق دوست پالیسی، پولیس و جیل اصلاحات، تشدد کی مطلق ممانعت، اور انٹیلی جنس اداروں کی پارلیمانی نگرانی—یہ سب دکھاوے کے منشور نہیں، ریاستی بقا کے تقاضے ہیں۔ عدلیہ کے لیے واضح ضابطۂ کار، ازخود نوٹس کی معقول حد بندی، بنچ تشکیل کے شفاف اصول، کیس مینجمنٹ کے اجلاسی اہداف، اور ججز کی جوابدہی کے خوف کے بغیر مگر ذمہ دارانہ نظام—یہ سب عدالتی وقار کے خلاف نہیں، اسی کے حق میں ہے۔ معیشت کے باب میں این ایف سی اور صوبائی مالی خودمختاری پر مکالمہ ممنوعات میں نہیں، اعتماد سازی میں ہونا چاہیے—اعداد و شمار کھلے، فارمولے واضح، عبوری انتظامات وقت بند، اور سیاسی رعایتوں کے بجائے کارکردگی کے اشاریے بنیاد بنیں۔اصل تنبیہ یہی ہے: طاقت کے محاورے اور محور بدلتے رہتے ہیں۔ آج جو اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگا—اور وہ آپ ہی کے وضع کردہ قواعد سے آپ کا حساب لے گا۔ اس لیے آئین کو اپنی سہولت کے سانچے میں ڈھالنے کے بجائے اپنے آپ کو آئین کے سانچے میں ڈھالیں۔ سیاست اگر “جیتنے کی سائنس” بنی رہے گی اور “حکمرانی کی اخلاقیات” نہ بنے گی تو انجام وہی ہوگا جس سے آپ خود ڈراتے ہیں: مطلق نراجیت۔ ریاستیں قانون سے چلتی ہیں، ارادوں سے نہیں؛ ادارے قواعد سے مضبوط ہوتے ہیں، وفاداریوں سے نہیں؛ اور جمہوریت رائے سے بنتی ہے، رعایت سے نہیں۔آج بھی وقت ہے کہ سیاسی قیادت آئین کی بالادستی کو نعرے سے آگے لے جا کر عمل کا ضابطہ بنائے۔ اختلاف کو جرم نہ بنائے، صحافت کو دشمن نہ سمجھے، عدالتوں کو ہتھیار نہ بنائے، انتخاب کو جنگ نہ سمجھے۔ وگرنہ تاریخ کی لکیر لمبی ضرور ہے، مگر وہ ہر بار اسی نکتے پر آ کر مل جاتی ہے جہاں سے ہم چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں—اور تب “اصلاح” کے سب عنوان دھندلا جاتے ہیں، باقی رہ جاتی ہے ریاست کا وہ بوسیدہ ڈھانچہ جسے ہم بار بار اپنے ہاتھوں سے کمزور کرتے آئے ہیں۔ ابھی بھی دسترس میں وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم اپنے کل کو بدنامی کے مقدمے سے بچا سکتے ہیں: اصول، ادارہ، اور احتساب—خود سے شروع کر کے۔ یہی وقت ہے، اس سے آگے پھر شاید صرف وقت ہی رہ جائے۔
قانون پر عمل کرنے کی سزا؟
پاکستان میں طاقتور طبقوں کے اثر و رسوخ کی کہانیاں کوئی نئی نہیں، مگر جب یہ اثر و رسوخ براہِ راست ریاستی اداروں کے ایماندار افسران کو نشانہ بناتا ہے، تو یہ نہ صرف ادارہ جاتی کمزوری بلکہ ریاستی مفادات کے کھلے عام سودا کرنے کا عندیہ دیتا ہے۔ حالیہ دنوں میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) نے کراچی سے اپنے دو افسران کا اسلام آباد تبادلہ کیا، بظاہر یہ ایک معمول کی کارروائی بتائی گئی۔ تاہم دستیاب اطلاعات اور خود متاثرہ افسران کے بیانات سے ایک مختلف کہانی سامنے آتی ہے—ایک ایسی کہانی جو ہمارے ٹیکس نظام، پالیسی سازی اور حکومتی عزم پر سنگین سوالات اٹھاتی ہے۔ان میں سے ایک افسر نے واضح طور پر بتایا کہ جب انہوں نے گاڑیوں کی درآمد میں بینامی لین دین، بیگیج اور گفٹ اسکیم کے ناجائز استعمال کے خلاف سخت کارروائی کی، تو یہ اقدامات طاقتور لابیوں کو ناگوار گزرے۔ ان کے مطابق ان کا “قصور” صرف یہ تھا کہ انہوں نے قانون پر عمل کرایا اور قومی خزانے کو نقصان سے بچایا۔ دوسری جانب دوسرے افسر کا آڈٹ رپورٹ بھی نہایت چشم کشا ہے جس میں بتایا گیا کہ گاڑیوں کے درآمد کنندگان مسلسل اس بات کا ثبوت دینے میں ناکام رہے کہ ان کی خریداری کے لیے رقوم جائز غیر ملکی ذرائع سے آئی ہیں۔یہ دونوں معاملات محض چند افراد کی کہانیاں نہیں بلکہ اس وسیع تر ڈھانچے کی علامت ہیں جس میں اشرافیہ کی گرفت تین سطحوں پر برقرار ہے۔ اول، ہمارا ٹیکس نظام آج بھی بالواسطہ ٹیکسوں پر زیادہ انحصار کرتا ہے، جس کا بوجھ غریب پر امیر کی نسبت کہیں زیادہ پڑتا ہے۔ یہ غیر منصفانہ ڈھانچہ غربت کی شرح کو 44.2 فیصد تک پہنچا چکا ہے۔ دوم، بجٹ کا بڑا حصہ ایسے طبقے کے حق میں مختص کیا جاتا ہے جو عوامی خزانے سے تنخواہیں اور پنشن لیتا ہے، اور جن کی آمدن ہر سال مہنگائی کی شرح سے کہیں زیادہ بڑھا دی جاتی ہے—جبکہ 93 فیصد محنت کشوں کی آمدن میں کووڈ-19 کے بعد کوئی اضافہ نہیں ہوا، اور 22 فیصد بے روزگاری کے ساتھ مزید نوکریاں ختم ہونے کا اندیشہ موجود ہے۔ سوم، پالیسی سازی کے عمل میں اشرافیہ کے مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے، جس کی مثال چینی کے نرخوں میں بار بار اضافہ ہے، جہاں مل مالکان کے فراہم کردہ غلط اعداد و شمار پر برآمدات کی اجازت دے دی جاتی ہے، حالانکہ فیصلہ ساز بخوبی اس حقیقت سے واقف ہوتے ہیں۔ایف بی آر کے ان دو افسران کا تبادلہ اسی ذہنیت کی جھلک پیش کرتا ہے—قانون دوسروں کے لیے، مگر طاقتوروں کے لیے نہیں۔ بلاشبہ سرکاری اداروں میں تبادلے اور تقرریاں معمول کا حصہ ہیں، لیکن ان اقدامات کے وقت اور پس منظر نے شکوک پیدا کر دیے ہیں۔ اگر یہ واقعی معمول کا تبادلہ تھا، تب بھی اس کے اثرات منفی ہیں، کیونکہ یہ ایک واضح پیغام دیتا ہے کہ جو افسر طاقتوروں کے مفادات کو چیلنج کرے گا، وہ اپنی موجودہ ذمہ داری پر برقرار نہیں رہ سکے گا۔یہاں ایف بی آر کے چیئرمین رشید لنگڑیال کا کردار نہایت اہم ہو جاتا ہے، جو حالیہ بیانات میں ٹیکس چوروں کے خلاف سخت کارروائی کے دعوے کر چکے ہیں۔ اگر یہ تبادلے واقعی غیر معمولی دباؤ کا نتیجہ ہیں تو فوری طور پر انہیں واپس لینا چاہیے۔ اور اگر یہ محض اتفاق ہے، تب بھی ضروری ہے کہ ان افسران کو کراچی میں اپنے فرائض انجام دینے کی اجازت دی جائے، تاکہ ایک مضبوط پیغام جائے کہ قانون کے نفاذ میں کسی کو استثنا حاصل نہیں اور ایماندار افسران کے پیچھے ان کے ادارے کی مکمل حمایت موجود ہے۔مزید برآں، اس واقعے نے ایک اہم ضرورت کو اجاگر کیا ہے—تمام سرکاری اداروں کو ایک واضح نظام اور طریقہ کار وضع کرنا ہوگا جس کے تحت کسی بھی افسر کو یہ حق ہو کہ وہ قانون کی خلاف ورزی کے لیے ڈالا گیا دباؤ اپنی سینئر انتظامیہ کے علم میں تحریری طور پر لا سکے۔ اس طرح، اگر کسی افسر کا تبادلہ یا سزا دی جاتی ہے تو اس کے پاس ثبوت موجود ہو کہ اس نے بروقت آگاہ کیا تھا۔آخر میں سوال وہی ہے جو برسوں سے ہمارے سیاسی و انتظامی ڈھانچے کے گرد گردش کر رہا ہے: کیا ہم ایک ایسے نظام کی طرف بڑھ سکتے ہیں جہاں قانون سب کے لیے برابر ہو، یا پھر طاقتور طبقات کی لامحدود مراعات اور اثر و رسوخ اسی طرح قانون کو یرغمال بناتے رہیں گے؟ اگر ہم واقعی ایک شفاف اور جوابدہ ریاست چاہتے ہیں تو ہمیں محض نعرے نہیں بلکہ عملی اقدامات کے ذریعے یہ یقین دہانی کرانی ہوگی کہ ایمانداری کو سزا نہیں بلکہ انعام ملتا ہے۔