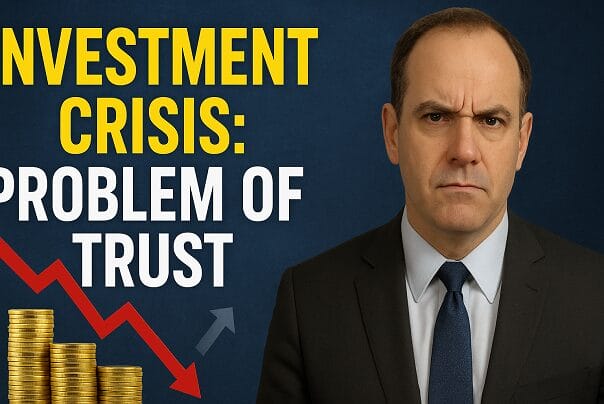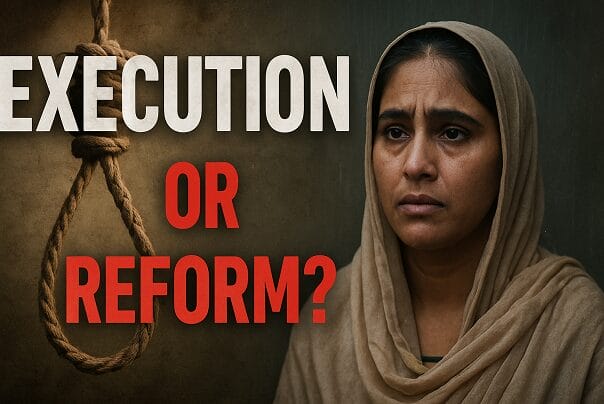پاکستان کی معیشت میں زراعت کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی سی رہی ہے۔ یہ وہ شعبہ ہے جس پر نہ صرف دیہی معیشت بلکہ لاکھوں خاندانوں کی زندگی اور ملک کی غذائی خودکفالت کا انحصار ہے۔ مگر آج یہ شعبہ شدید بحران کا شکار ہے۔ حالیہ دنوں میں پاکستان کسان اتحاد کی جانب سے پیش کی گئی تفصیلات نے اس تباہی کو مزید واضح کر دیا ہے۔ ایک طرف بڑھتی ہوئی پیداواری لاگت، غیر مؤثر حکومتی پالیسیاں اور پانی کی قلت جیسے مسائل ہیں، تو دوسری طرف موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں غیر متوقع بارشیں، گرمی کی شدت اور فصلوں کی بربادی نے کسانوں کو بےبس کر دیا ہے۔
کسان اتحاد کے مطابق گزشتہ کچھ برسوں میں چاول، مکئی اور آم جیسی اہم برآمدی فصلوں کی پیداوار اور برآمدات میں نمایاں کمی آئی ہے، جس سے نہ صرف زرِ مبادلہ میں کمی واقع ہوئی بلکہ ملک میں غذائی عدم تحفظ کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے۔ گندم کی آئندہ فصل سے متعلق بھی خدشات کا اظہار کیا گیا ہے کیونکہ حکومت نے سپورٹ پرائس یا امدادی قیمت کا نظام ختم کر دیا ہے، جو ہمیشہ کسان کو ایک معاشی تحفظ فراہم کرتا رہا ہے۔ یہ صورت حال صرف فصلوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ اب دیہی علاقوں میں غربت، بے روزگاری اور عدم مساوات کے اضافے کا اندیشہ بھی پیدا ہو گیا ہے — ایک ایسا خطرہ جو آخرکار سماجی اور سیاسی عدم استحکام کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔
زراعت سے جڑے بحران کے اسباب میں سب سے بڑا مسئلہ پالیسی سازی کی کمزوری اور ناقص عمل درآمد ہے۔ حکومت کی جانب سے وقتاً فوقتاً اعلان کیے گئے مراعاتی پیکجز اکثر محض دعووں کی حد تک محدود رہتے ہیں، جن کا زمین پر کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ زرعی پیداوار کی شرح پچھلے پندرہ سالوں سے تقریباً جمود کا شکار ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گندم، کپاس، مکئی، گنا اور چاول جیسی بڑی فصلوں کی سالانہ ترقی کی شرح بمشکل ایک فیصد سے کچھ ہی زیادہ رہی ہے۔ دوسری جانب پھل اور سبزیاں بھی ترقی کے اس دائرے میں نہیں آ رہیں جس کی ان سے توقع کی جاتی تھی۔ اس دوران صرف مویشی پالنے کے شعبے میں کچھ حد تک بہتری دیکھی گئی ہے، مگر وہ پورے زرعی شعبے کا بوجھ اٹھانے کے لیے کافی نہیں۔پاکستان کسان اتحاد نے اپنی حالیہ پریس کانفرنس میں حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فصلوں پر کم از کم 25 فیصد منافع کو یقینی بنایا جائے، آبپاشی کے لیے بجلی کے نرخوں میں کمی کی جائے، اور بنیادی فصلوں و سبزیوں کے لیے منصفانہ مارکیٹ قیمتیں طے کی جائیں تاکہ کسان دوبارہ کھیت میں واپس آئے اور فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ممکن ہو۔ یہ مطالبات بظاہر جائز اور بنیادی لگتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سوچنے والا پہلو یہ بھی ہے کہ کیا صرف سبسڈی، رعایت یا امدادی قیمت کے ذریعے ہم زرعی بحران پر قابو پا سکتے ہیں؟
حقیقت یہ ہے کہ مسئلے کی جڑ گہری ہے اور اس کے حل کے لیے روایتی اندازِ فکر سے ہٹ کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ حکومت کی سرپرستی والا موجودہ زرعی نظام اب فرسودہ ہو چکا ہے۔ اس نظام نے نہ کسان کو خودمختار بنایا، نہ زمین کو زرخیز رکھا، اور نہ ملک کو زرعی لحاظ سے خودکفیل بنا سکا۔ آج جب دنیا زرعی ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل معلومات اور جدید تحقیقی بنیادوں پر زراعت کو بہتر بنا رہی ہے، تو ہم اب بھی بیج کے معیار، پانی کی تقسیم اور فرسودہ مشینری کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔
زراعت کا بحران صرف کسان کا مسئلہ نہیں، یہ پوری معیشت، خوراک کی خودکفالت اور دیہی معاشرت کے بقا کا سوال ہے۔ اگر ہم نے اب بھی اس تباہی کا ادراک نہ کیا، تو صرف فصلیں نہیں جلیں گی، پورا معاشرتی ڈھانچہ درہم برہم ہو جائے گا۔
پاکستان کی زراعت کو بحران سے نکالنے کے لیے محض وقتی مراعات یا امدادی پیکجز کافی نہیں۔ ضرورت ایک ہمہ جہت، طویل المدتی اور پائیدار اصلاحاتی حکمتِ عملی کی ہے، جو اس شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرے۔ سب سے پہلے حکومت کو زرعی پالیسیوں کو وقتی سیاسی مفادات سے الگ کر کے ایک قومی ترجیح بنانا ہوگا۔ مستقل زرعی پالیسی کا قیام، جسے ہر حکومت تسلسل سے نافذ کرے، اولین ضرورت ہے۔
زرعی تحقیق و ترقی میں سرمایہ کاری بڑھانا، جدید بیجوں اور موسمیاتی تبدیلی کے موافق فصلوں کی تیاری، اور کسانوں کو نئی زرعی ٹیکنالوجی سے روشناس کروانا بنیادی اصلاحات کا حصہ ہونا چاہیے۔ دیہی علاقوں میں سڑکیں، ذخیرہ گاہیں، اور منڈی تک رسائی بہتر بنانا بھی ضروری ہے تاکہ کسان کو اپنی پیداوار کی درست قیمت مل سکے۔
ساتھ ہی، چھوٹے کسانوں کو بلاسود یا کم شرح سود پر قرضے فراہم کرنے، اور فصلوں کی بیمہ اسکیموں کو فعال بنانے سے ان کا معاشی تحفظ ممکن ہے۔ حکومت کو پانی کے انتظام میں شفافیت، بجلی کے نرخوں میں توازن، اور زمین کی اصلاحات پر بھی توجہ دینی ہوگی۔
نجی شعبے کو زراعت میں سرمایہ کاری کی دعوت دے کر، اور ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دے کر ہم زراعت کو جدید اور منافع بخش بنا سکتے ہیں۔
یہ صرف کسان کی فلاح کا مسئلہ نہیں، بلکہ پاکستان کی غذائی سلامتی، معیشت کی بنیاد اور دیہی معاشرت کی بقا کا سوال ہے۔ اگر ہم نے اب بھی سنجیدہ اصلاحات نہ کیں، تو زراعت کی تباہی پورے معاشی نظام کو ساتھ لے ڈوبے گی۔ ریاست کو اب جاگنا ہوگا۔
کیا واقعی ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح بڑھی ہے؟
حالیہ دنوں میں وزیرِاعظم شہباز شریف کو فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی جانب سے دی جانے والی ہفتہ وار بریفنگ میں یہ دعویٰ سامنے آیا کہ پاکستان کی ٹیکس آمدنی کا مجموعی قومی پیداوار (جی ڈی پی) سے تناسب یعنی ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح 1.5 فیصد پوائنٹس بڑھ کر 10.5 فیصد تک پہنچ چکی ہے۔ اس اضافہ کو حکومت کی بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) کے ساتھ طے شدہ تین سالہ اصلاحاتی منصوبے کے اہداف کی جانب ایک “بڑی پیش رفت” قرار دیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آیا یہ اضافہ حقیقتاً معیشت کی بہتری کی عکاسی کرتا ہے، یا محض عددی ہنر بندی کا نتیجہ ہے۔
2024-25 کے بجٹ میں ایف بی آر کی کل ٹیکس آمدنی 11,900 ارب روپے دکھائی گئی، جبکہ اسی عرصے کے لیے نظرثانی شدہ جی ڈی پی 114,692 ارب روپے بیان کی گئی، جو کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی تناسب کو 10.3 فیصد پر لے آتی ہے — نہ کہ دعوے کے مطابق 10.5 فیصد پر۔ مزید برآں، مالی سال کے اختتام پر ایف بی آر نے خود تسلیم کیا کہ اس کی عبوری وصولیاں 11,722 ارب روپے رہی ہیں، جو کہ مجموعی جی ڈی پی کا صرف 10.2 فیصد بنتی ہیں۔ گویا 178 ارب روپے کی کمی کے باوجود، اس شرح میں “اضافے” کا تاثر کس بنیاد پر دیا گیا، یہ وضاحت طلب ہے۔
دوسری اہم بات یہ ہے کہ جس “شرحِ نمو” کے تحت ٹیکس ٹو جی ڈی پی تناسب میں 1.5 فیصد اضافہ دکھایا جا رہا ہے، وہ دراصل اس لیے ممکن ہوئی کہ ملک کی معیشت نے وہ رفتار اختیار ہی نہیں کی جو بجٹ میں پیش گوئی کی گئی تھی۔ معاشی سست روی، شرحِ سود کی بلند سطح، اور سخت مالیاتی پالیسیوں نے جی ڈی پی کو سکڑنے پر مجبور کیا، جس کے نتیجے میں جی ڈی پی کا حجم توقع سے 9,468 ارب روپے کم رہا۔ اگر بجٹ کے مطابق معیشت کی ترقی ہوتی، تو یہی ٹیکس کلیکشن ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح کو 9.5 فیصد پر برقرار رکھتی — یعنی کوئی اضافہ دکھائی ہی نہ دیتا۔
مزید تشویشناک امر یہ ہے کہ حکومت کی تمام تر اصلاحاتی کوششیں صرف ٹیکس آمدنی بڑھانے تک محدود ہیں، جبکہ ٹیکس نظام کی بنیادی خامیاں جوں کی توں موجود ہیں۔ پاکستان کا موجودہ ٹیکس نظام نہ صرف غیر منصفانہ ہے بلکہ شدید طور پر بالواسطہ ٹیکسوں پر انحصار کرتا ہے، جو معاشی طور پر کمزور طبقے پر زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں۔ ایف بی آر کی براہِ راست ٹیکس وصولیوں کا 75 سے 80 فیصد حصہ وہ ہے جو دراصل سیلز ٹیکس کے انداز میں منہا کیا جاتا ہے، یعنی بالواسطہ ٹیکس — جس کی شدت امیروں کے مقابلے میں غریبوں پر زیادہ ہوتی ہے۔
بدقسمتی سے، آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ہدایت کے باوجود ایف بی آر ان بالواسطہ ٹیکسوں کو براہِ راست ٹیکس کے خانے میں شمار کرتا رہا ہے، جس سے نہ صرف مالیاتی حقائق مسخ ہوتے ہیں بلکہ پالیسی سازی بھی غلط بنیادوں پر استوار ہوتی ہے۔ اس کے برعکس، ایف بی آر اور حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ اس ظالمانہ ٹیکس ڈھانچے کی اصلاح پر توجہ دیتی، جو کہ ایک محدود طبقے کو فائدہ پہنچاتا ہے اور وسیع آبادی کو محرومی میں دھکیلتا ہے۔
یہ بات بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ ایف بی آر کو بجٹ 2025 کے تحت دیے گئے نئے اختیارات، اگرچہ پارلیمانی کمیٹی نے ان میں ترمیم کی ہے، مگر اب بھی صنعتکاروں اور تاجروں کی طرف سے ان پر شدید اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ ان اختیارات پر عمل درآمد التوا کا شکار ہے، اور ان کا مستقبل غیر یقینی ہے۔
خلاصہ یہی ہے کہ اگر ٹیکس نظام میں بنیادی ڈھانچوں کی اصلاح نہ کی گئی اور صرف موجودہ ٹیکس دہندگان پر مزید بوجھ ڈال کر اہداف حاصل کرنے کی روش برقرار رہی، تو نہ صرف ٹیکس دہندگان کا اعتماد مزید مجروح ہوگا بلکہ معیشت کا بوجھ بھی ناقابل برداشت ہوتا چلا جائے گا۔ وقت آ گیا ہے کہ ایف بی آر محض ہدف حاصل کرنے کی مشق سے نکل کر ٹیکس نظام کو منصفانہ، شفاف اور ترقی پسند بنانے پر توجہ دے — ورنہ 13 فیصد کا ہدف بھی محض ایک فریب ہی بن کر رہ جائے گا۔