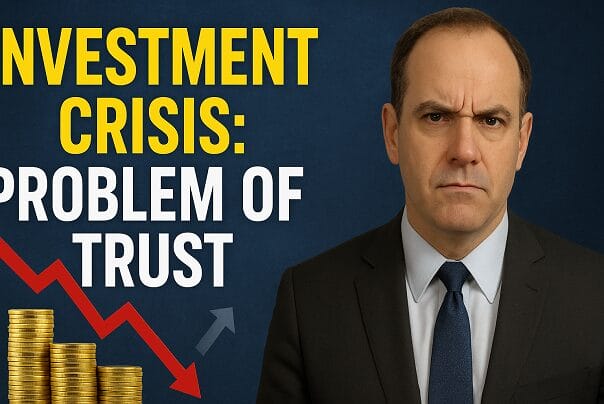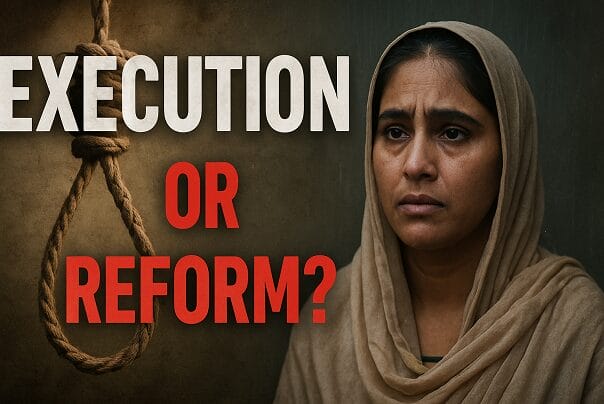امریکا اور پاکستان کے درمیان حالیہ تجارتی و توانائی معاہدے کو ایک ’’تاریخی سنگِ میل‘‘ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسے ایک “لینڈ مارک” معاہدہ قرار دیا ہے، اور سرکاری بیانات میں اسے دوطرفہ تعلقات میں نئے باب کے آغاز سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس معاہدے میں نہ صرف تجارت کو وسعت دینے بلکہ پاکستان میں تیل کی تلاش اور ترقی کے لیے امریکی تعاون کی بات کی گئی ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود، احتیاط اور حقیقت پسندی کے بغیر اس نئی گرمجوشی کو مکمل کامیابی قرار دینا قبل از وقت ہوگا۔
پاکستان اور امریکا کے تعلقات تاریخی طور پر سیکورٹی پر مبنی اور باہمی مفادات کی بنیاد پر عارضی نوعیت کے رہے ہیں۔ افغانستان کے بعد کا دور، خاص طور پر ٹرمپ دور میں، ان تعلقات میں سرد مہری کا عکاس رہا۔ اب جب کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 30 جولائی کو پاکستان کے ساتھ تیل کے ذخائر کی مشترکہ ترقی کا اعلان کیا ہے، اور ساتھ ہی پاکستان نے امریکا سے ایک تجارتی معاہدے کی بھی تصدیق کی ہے، تو یہ ضرور ایک مثبت پیش رفت ہے۔
تاہم، اس معاہدے کے جوش و خروش میں ہمیں چند زمینی حقائق کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے پاکستانی برآمدات پر 29 فیصد سے کم ہو کر 19 فیصد ٹیرف کی تصدیق بظاہر خوش آئند ہے، لیکن یہ اب بھی ایسا ٹیرف ہے جو پاکستان کی برآمدی صلاحیت پر گہرے اثرات ڈال سکتا ہے۔ ہماری صنعتیں پہلے ہی بلند پیداواری لاگت، کم تکنیکی استعداد اور توانائی کے بحران سے دوچار ہیں۔ مزید یہ کہ پاکستان کی برآمدات کی سب سے بڑی منزل امریکا ہے، اور ہمارے برآمدی بازاروں میں تنوع نہ ہونے کے باعث کسی بھی منفی تجارتی جھٹکے کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔
اس تناظر میں ان بیانات پر بھی نظرِ ثانی ضروری ہے جو بھارت پر عائد 25 فیصد امریکی ٹیرف کو پاکستان کے لیے ’’موقع‘‘ قرار دیتے ہیں۔ بھارت کی مضبوط صنعتی بنیاد، مؤثر لاگت کی حکمت عملی، اور وسیع تجارتی شراکت داری اسے ایسے جھٹکوں کو جذب کرنے کی صلاحیت دیتی ہے — جب کہ پاکستان ان شعبوں میں کہیں پیچھے ہے۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ بھارت نے روس سے تیل کی درآمدات میں کمی لا کر واشنگٹن کی ناراضی کو کم کرنے کی سنجیدہ کوشش کی ہے، جس کے بعد کسی بھی “خالی جگہ” کا تصور اب زیادہ مبالغہ آمیز لگتا ہے۔
معاہدے کا ایک اہم پہلو توانائی کے شعبے میں امریکی سرمایہ کاری سے متعلق ہے۔ پاکستان کی معدنیاتی دولت، خصوصاً انڈس بیسن میں موجود شیل آئل اور گیس کے ذخائر، تاحال بڑی حد تک غیر استعمال شدہ ہیں۔ امریکی توانائی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کی 2015 کی رپورٹ اس خطے کو توانائی کے ایک ممکنہ مرکز کے طور پر دیکھتی ہے، لیکن ہمارے اپنے ادارے وسائل، مہارت اور سرمایہ کاری کی کمی کے باعث ان مواقع کو استعمال کرنے سے قاصر ہیں۔ اس صورت میں اگر امریکا واقعی سنجیدگی سے تکنیکی معاونت، سرمایہ، اور انتظامی شراکت کے ساتھ شریک ہو، تو یہ تعاون پاکستان کے توانائی بحران میں خاطر خواہ بہتری لا سکتا ہے۔
مگر ہمیں ماضی کے تجربات سے بھی سبق سیکھنا ہوگا۔ سابقہ حکومتوں، خصوصاً پی ٹی آئی دور میں بھی، معدنیاتی ترقی کی بلند بانگ دعوے کیے گئے تھے، مگر وہ سب امیدیں سیاسی عدم تسلسل، بیوروکریٹک سست روی، اور پالیسی کی غیر شفافیت کے باعث دم توڑ گئیں۔ لہٰذا اس نئے معاہدے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے صرف اعلان کافی نہیں، بلکہ اس کے ہر مرحلے میں شفاف، غیر مبہم اور متفقہ طریقہ کار ضروری ہے — خاص طور پر آمدن کی تقسیم، اخراجات کی نگرانی، اور شراکت داروں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے۔
ایک اور حساس پہلو جو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے وہ ہے صوبوں کا کردار۔ آئین کے تحت معدنی وسائل کی تلاش اور ترقی بنیادی طور پر صوبائی دائرہ اختیار میں آتی ہے۔ اگر اس معاہدے میں صوبوں کو اعتماد میں نہ لیا گیا، یا ان کے آئینی کردار کو پسِ پشت ڈالا گیا، تو نہ صرف اس منصوبے کو اندرونی مزاحمت کا سامنا ہوگا، بلکہ وفاقی-صوبائی تعلقات میں بھی نئی دراڑیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ معاہدے کی تفصیلات سامنے لائی جائیں اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر پالیسی وضع کی جائے۔
پاکستان کی اقتصادی تاریخ ایسے وعدوں سے بھری پڑی ہے جو ابتدا میں انقلابی لگتے تھے، مگر عملی میدان میں ناکامی کا شکار ہوئے۔ اس نئے امریکی معاہدے میں کئی امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں — برآمدات میں اضافہ، توانائی کے بحران میں کمی، اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں بہتری — مگر اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے محض الفاظ کافی نہیں۔
اقتصادی پالیسی سازوں کو چاہیے کہ وہ اس معاہدے کو صرف سیاسی کامیابی کے طور پر نہ برتیں، بلکہ حقیقت پسندانہ انداز میں اس کی پیچیدگیوں کو سمجھیں۔ امریکی برآمدات سے متعلق ٹیرف میں کمی ایک مثبت پیش رفت ہے، مگر جب تک پاکستان اپنے پیداواری ڈھانچے، لاگت کے نظام، اور تجارتی تنوع میں بنیادی اصلاحات نہیں لاتا، کوئی بھی سہولت وقتی فائدہ تو دے سکتی ہے، پائیدار ترقی نہیں۔
اسی طرح، امریکا سے ایک ملین بیرل خام تیل کی درآمد کے اعلان کو اسٹرٹیجک کامیابی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس سے پاکستان کے زرِمبادلہ کے ذخائر پر دباؤ بڑھے گا، خاص طور پر جب مال برداری اور ادائیگی کے اخراجات زیادہ ہوں گے۔ ہمیں توانائی کی خریداری میں توازن اور حکمت عملی کی اشد ضرورت ہے، تاکہ وقتی فائدہ طویل المدت نقصان میں نہ بدل جائے۔
آخر میں، اگرچہ معاہدے کی تفصیلات ابھی تک مکمل طور پر سامنے نہیں آئیں، تاہم یہ ضروری ہے کہ اس کا اطلاق شفاف، آئینی اور زمینی حقائق سے ہم آہنگ طریقے سے ہو۔ تمام سیاسی، انتظامی، اور علاقائی فریقین کی شمولیت کے بغیر کسی بھی منصوبے کی کامیابی مشکوک ہوتی ہے۔ اس معاہدے کی کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ کیا ہم ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے کے لیے تیار ہیں، یا ایک بار پھر امید کے پردے میں حقیقت کو دفن کرنے جا رہے ہیں۔
نئے اقتصادی مواقع دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، مگر ان کی گھنٹی صرف سننے سے کچھ نہیں ہوگا — دروازہ کھولنا پڑے گا، اور اندر آنے والے مہمان کے ساتھ میزبان جیسا برتاؤ بھی کرنا ہوگا۔ شفافیت، استعداد، اور اجتماعی مفاد کو اگر اولین ترجیح بنالیا جائے، تو شاید یہ معاہدہ صرف وعدہ نہ رہے — بلکہ ایک حقیقت بن جائے۔
تحریک طالبان پاکستان کا پھیلاؤ
خیبرپختونخوا، بالخصوص سابقہ فاٹا کے علاقے، گزشتہ دو دہائیوں سے ایک مسلسل جنگی کیفیت کا سامنا کر رہے ہیں۔ پرویز مشرف کے دور سے لے کر آج تک یہ خطہ عسکریت پسندی، دہشتگردی، اور ریاستی فوجی کارروائیوں کی زد میں ہے۔ پاکستانی فوج نے دہشتگرد گروہوں کے خلاف کئی بار کمر کس کر کارروائیاں کیں، کچھ کامیابیاں بھی حاصل ہوئیں، لیکن اس کے باوجود تحریک طالبان پاکستان (TTP) جیسا خطرناک گروہ مکمل طور پر ختم نہ ہو سکا۔ آج بھی بعض علاقوں میں ٹی ٹی پی کی موجودگی ایک زندہ حقیقت ہے، جیسے حالیہ اطلاعات کے مطابق، تیراہ کے مقامی قبائل نے وہاں موجود طالبان جنگجوؤں سے علاقہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جواب میں ان جنگجوؤں نے کہا کہ وہ اپنے امیر سے، جو کہ افغانستان میں ہے، مشورہ کریں گے۔ اس مختصر واقعے میں کئی پرتیں پوشیدہ ہیں: اول، یہ کہ طالبان آج بھی عوامی علاقوں میں دندناتے پھر رہے ہیں؛ دوم، ٹی ٹی پی کا قیادت ڈھانچہ آج بھی افغانستان میں محفوظ ہے اور فعال ہے۔
یہ حقیقت اس بات کو مزید تقویت دیتی ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت کے آنے کے بعد پاکستان کے لیے خطرات میں اضافہ ہوا ہے۔ دہشتگردوں کو وہاں سے نہ صرف نظریاتی سہارا ملتا ہے بلکہ لاجسٹک مدد بھی حاصل ہوتی ہے۔ اگر پاکستانی ریاست اس حقیقت سے چشم پوشی کرے تو وہ نہ صرف اپنی سکیورٹی کو خطرے میں ڈالے گی بلکہ اس خطے کے وسیع تر استحکام کو بھی دائو پر لگا دے گی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنے سالوں کے فوجی آپریشنز، ہزاروں جانوں کی قربانی، اور اربوں روپے کے اخراجات کے باوجود دہشتگردی جڑ سے کیوں نہ اکھاڑی جا سکی؟
اس کی ایک بڑی وجہ انسداد دہشتگردی کی پالیسیوں میں ہم آہنگی کا فقدان ہے۔ “کلیئر، ہولڈ اور بلڈ” کی جو حکمتِ عملی اپنائی گئی، اس کا پہلا اور دوسرا مرحلہ تو کسی حد تک کامیاب رہا، لیکن تیسرا اور سب سے اہم مرحلہ — یعنی “بلڈ”، یعنی ریاستی اداروں کا قیام، سول حکمرانی کی بحالی، اور عوام کا اعتماد حاصل کرنا — شدید طور پر ناکام ہوا۔ جب تک قبائلی علاقوں میں مقامی پولیس، عدالتیں، صحت، تعلیم، اور روزگار جیسے بنیادی ڈھانچے کا قیام نہیں ہوگا، عسکریت پسندی کا خلا کبھی پُر نہ ہو سکے گا۔ یہ خلا دہشتگرد گروہ بخوبی استعمال کرتے ہیں اور ایک متبادل نظام کے طور پر خود کو پیش کرتے ہیں، جو مقامی افراد کو وقتی تحفظ یا انصاف تو دے سکتا ہے، لیکن درحقیقت وہ معاشرے کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔
اس ناکامی کی ذمہ داری مکمل طور پر فوج پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ سول حکومتیں، خواہ وہ وفاقی سطح پر ہوں یا صوبائی، مسلسل اس پہلو کو نظر انداز کرتی رہی ہیں کہ ہر عسکری کامیابی کے پیچھے ایک سول ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ فاٹا کا انضمام صرف قانونی طور پر مکمل ہوا؛ عملی طور پر وہ خطہ اب بھی ایک نیم خودمختار، کم ترقی یافتہ، اور ریاست سے بدظن علاقہ بنا ہوا ہے۔ یہ وہ خلاء ہے جس میں ٹی ٹی پی جیسے گروہ پنپتے ہیں۔
حالیہ دنوں میں باجوڑ کے قبائلی ضلع میں شروع کی جانے والی آپریشن سربکف ایک بار پھر اس تلخ حقیقت کو اجاگر کرتی ہے کہ ریاست کو ہر چند سال بعد انہی علاقوں میں دوبارہ طاقت کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ مقامی آبادی کی طرف سے آپریشن کے خلاف احتجاج اور کرفیو کے خلاف شکایات اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ اعتماد کا فقدان کتنا گہرا ہے۔ اہلِ علاقہ کی شکایت ہے کہ نہ تو انہیں بروقت مطلع کیا گیا، نہ ہی ان کے تحفظ کو مقدم جانا گیا۔ یہی وہ عوامل ہیں جو عسکریت پسندی کے خلاف ریاستی اقدامات کو مشکوک بنا دیتے ہیں، اور اس تحریک کو عوامی حمایت حاصل کرنے کا موقع دیتے ہیں۔
یہ بات خاص طور پر قابلِ توجہ ہے کہ خیبرپختونخوا کی حکومت، جو پاکستان تحریک انصاف کے زیر قیادت ہے، ابتدا میں اس آپریشن کی مخالفت کرتی رہی، مگر پھر ایک غیر متوقع یوٹرن لیتے ہوئے اس کی حمایت کا اعلان کر دیا گیا۔ لیکن پارٹی کی مرکزی قیادت آج بھی فوجی کارروائیوں کے خلاف بیان بازی کر رہی ہے، جس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ انسداد دہشتگردی کے معاملے پر سیاسی قیادت میں اتفاقِ رائے موجود نہیں۔ یہی وہ کمزوریاں ہیں جو عسکریت پسند گروہوں کو تقویت دیتی ہیں۔
عوام کا یہ سوال بالکل جائز ہے کہ دو دہائیوں سے جاری آپریشنز، ہزاروں شہادتوں اور اربوں کی لاگت کے باوجود ٹی ٹی پی جیسے گروہ دوبارہ کیسے منظم ہو گئے؟ اس کا ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریاست نے کبھی مکمل طور پر دہشتگردوں کے لیے سپلائی لائن بند نہیں کی، خاص طور پر افغانستان سے پاکستان میں دراندازی روکنے کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے۔ پاکستان کے سکیورٹی ادارے اگرچہ “کلیئر” اور “ہولڈ” مرحلے میں کامیاب دکھائی دیے، لیکن “بلڈ” مرحلے میں سول حکومت کی شراکت نہ ہونے کے باعث یہ کامیابیاں عارضی ثابت ہوئیں۔
اسی وجہ سے عوام میں مایوسی پائی جاتی ہے اور وہ دونوں فریقین — دہشتگردوں اور فوج — کے خلاف سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ ان کے مظاہرے نہ صرف امن کی خواہش کا اظہار ہیں بلکہ ریاست کو ایک واضح پیغام بھی دیتے ہیں: کہ انہیں اب مزید لاشیں نہیں چاہییں، انہیں امن، روزگار اور تحفظ چاہیے۔
یہ مظاہرے درحقیقت ایک اجتماعی شعور کی عکاسی کرتے ہیں، جو انتہا پسندی، مذہبی عسکریت پسندی، اور ریاستی طاقت کے غیر متوازن استعمال کے خلاف ابھر رہا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ صرف بندوق سے نہیں جیتی جا سکتی؛ اس کے لیے عوامی اعتماد، شفاف سیاسی حکمتِ عملی، اور سول اداروں کی مضبوطی ناگزیر ہے۔
وزیراعظم کی زیرِ صدارت ‘ہارڈن دی اسٹیٹ کمیٹی کا حالیہ اجلاس امید کی ایک کرن فراہم کرتا ہے، بشرطیکہ اس میں طے شدہ نکات پر مکمل عمل درآمد ہو۔ دہشتگردی کے خلاف کثیرالجہتی حکمتِ عملی — جس میں عسکری کارروائی، قانون سازی، اور عوامی رابطہ شامل ہوں — وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ صرف فوجی کارروائیاں دہشتگردی کو جڑ سے اکھاڑنے میں ناکافی ہیں؛ اس کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عملدرآمد ناگزیر ہے۔
نیشنل ایکشن پلانمیں شامل نکات جیسے مدارس کی اصلاح، نفرت انگیز مواد پر پابندی، انتہا پسندی کے خلاف بیانیہ کی تشکیل، اور افغانستان کے ساتھ مؤثر سفارتی روابط وہ ستون ہیں جن پر ایک دیرپا انسداد دہشتگردی پالیسی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ مگر بدقسمتی سے ان نکات پر اکثر جزوی یا علامتی عمل ہوتا رہا ہے، جس سے نہ صرف دہشتگردوں کے حوصلے بلند ہوئے بلکہ ریاست کی ساکھ بھی متاثر ہوئی۔
اسی طرح، دہشتگردی کے خلاف اقدامات میں “کولیٹرل ڈیمیج” یعنی عوامی جان و مال کا نقصان، ایک ایسا پہلو ہے جسے فوری طور پر کم سے کم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر آپریشن میں بے گناہ افراد کی ہلاکتیں اور نقل مکانی ریاست پر سوالیہ نشان چھوڑتی ہیں۔ یہ لازم ہے کہ انسداد دہشتگردی کی کارروائیاں صرف شدت پسندوں تک محدود رہیں، اور ان کے نتائج عام شہریوں پر اثر انداز نہ ہوں۔
ٹی ٹی پی جیسے گروہوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے محض میدانِ جنگ میں کامیابی کافی نہیں؛ ہمیں نظریاتی سطح پر بھی ان کے بیانیے کو رد کرنا ہوگا۔ مدارس، مساجد، سوشل میڈیا، اور تعلیمی ادارے اس نظریاتی جنگ کے محاذ بن سکتے ہیں — بشرطیکہ ریاست سنجیدگی سے ان کی اصلاح کرے اور انہیں قومی بیانیے کی تشکیل میں شامل کرے۔
آخر میں، اگر ریاست اپنی مکمل رٹ قائم کرنا چاہتی ہے تو اسے ہر قسم کے غیرریاستی عناصر کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھنا ہوگا۔ چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، داعش، یا کوئی اور گروہ — ان سب کے خلاف ایک مربوط، شفاف، اور دیرپا پالیسی کی ضرورت ہے، جو صرف عسکری اداروں کی نہیں بلکہ پورے ریاستی ڈھانچے کی ذمہ داری ہے۔ جب تک ایسا نہ ہوگا، خیبرپختونخوا، بلوچستان، اور دیگر حساس علاقوں کے عوام امن و تحفظ کے لیے ترستے رہیں گے، اور دہشتگردی کی یہ اندھی رات مزید طویل ہوتی جائے گی۔
یوٹیلٹی سٹور ز کی بندش، بے روزگاری کا نیا طوفان
یوٹیلٹی اسٹورز کا قیام نصف صدی قبل پاکستان کی متوسط اور نچلے متوسط طبقے کے لیے ریاستی فلاح و بہبود کے تصور کا ایک ٹھوس مظہر تھا۔ یہ ادارہ اس وقت قائم کیا گیا جب ملک میں ریٹیل سیکٹر اپنی ابتدائی شکل میں تھا اور عام صارفین کو معیاری اشیائے خورونوش تک بآسانی اور ارزاں نرخوں پر رسائی حاصل نہیں تھی۔ ان اسٹورز کا بنیادی مقصد مارکیٹ کی مہنگائی اور طلب و رسد کے اتار چڑھاؤ سے کم آمدنی والے طبقے کو محفوظ رکھنا تھا۔ اس وقت جب سپر اسٹور یا چین ریٹیل نیٹ ورکس کا تصور نیا اور اجنبی تھا، یوٹیلٹی اسٹورز نے ایک منظم خریدارانہ ثقافت کو جنم دیا۔
تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ عظیم عوامی منصوبہ انتظامی بدحالی، بدعنوانی، ناقص نگرانی اور مالیاتی بے ضابطگیوں کا شکار ہو گیا۔ زیادہ تر دورانیے میں یہ ادارہ ایک ایسے سرکاری شعبے کی نمائندگی کرتا رہا جو صرف تنزلی کی مثال بن کر رہ گیا۔ وزارت خزانہ کی تازہ رپورٹ کے مطابق، گزشتہ مالی سال کی پہلی ششماہی میں یوٹیلٹی اسٹورز نے 4.1 ارب روپے کا خسارہ ظاہر کیا جبکہ مجموعی نقصان 15.5 ارب روپے تک جا پہنچا ہے۔
یہ صورتِ حال محض مالیاتی ناکامی نہیں بلکہ ایک وسیع تر ساختی اور انتظامی بحران کی نشاندہی کرتی ہے۔ حکومتوں کی جانب سے بارہا اس ادارے کی اصلاح کے دعوے تو کیے گئے، مگر عملی اقدامات نہ ہونے کے برابر رہے۔ ایک ایسا نیٹ ورک جو 4,000 اسٹورز پر مشتمل ہو، اور جس کا مقصد لاکھوں افراد تک روزمرہ ضرورت کی اشیاء سستے داموں پہنچانا ہو، وہ محض سرکاری نیک نیتی یا سبسڈی سے نہیں چلایا جا سکتا؛ اس کے لیے انتظامی اہلیت، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال، اور سخت مالی نظم و ضبط درکار ہوتا ہے — وہ تمام خوبیاں جو عمومی طور پر پاکستانی بیوروکریسی کے خمیر میں نہیں ملتیں۔
یوٹیلٹی اسٹورز کی بندش دراصل صرف ایک ادارے کا خاتمہ نہیں، بلکہ ریاستی فلاحی کردار کے سکڑتے دائرے کی ایک تلخ علامت ہے۔ جب ایک طرف روزگار کے مواقع کم ہو رہے ہوں، مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہو، اور عوامی اعتماد ریاستی اداروں سے اٹھ رہا ہو، ایسے میں اس نوعیت کا فیصلہ بے شمار معاشی اور سماجی جھٹکوں کو جنم دیتا ہے۔
یہ امر بھی قابل غور ہے کہ یوٹیلٹی اسٹورز کے ہزاروں ملازمین کی زندگیوں پر اس بندش کا کیا اثر پڑے گا۔ اگر ہر اسٹور پر اوسطاً دس ملازمین بھی فرض کیے جائیں، تو چالیس ہزار افراد براہ راست متاثر ہوں گے — اور ان کے خاندان بالواسطہ۔ یہ فیصلہ ان کے لیے نہ صرف معاشی موت بلکہ سماجی غیر یقینی کی علامت ہے۔
اس ساری صورتِ حال میں حکومت کی معاشی حکمتِ عملی پر سنجیدہ سوالات جنم لیتے ہیں۔ کیا ایسے فیصلے صرف خسارے کے اعداد و شمار دیکھ کر کیے جانے چاہئیں؟ یا ان کے سماجی اثرات کو بھی مدنظر رکھا جانا چاہیے؟ پبلک سیکٹر میں اصلاحات کی ضرورت سے انکار ممکن نہیں، مگر اس کے لیے جس متوازن اور واضح پالیسی فریم ورک کی ضرورت ہے، وہ تاحال نظر نہیں آتا۔
اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ یوٹیلٹی اسٹورز کی بندش کا فیصلہ ایک غیر شفاف عمل کے تحت کیا گیا۔ نہ تو پارلیمنٹ میں کھل کر بحث ہوئی، نہ عوامی رائے کو مدنظر رکھا گیا، اور نہ ہی متبادل روزگار یا سبسڈی ماڈل پر کوئی بامعنی بات چیت سامنے آئی۔ اس سے ایک ایسا پیغام جاتا ہے کہ عوام کی فلاح اب حکومت کی ترجیحات میں شامل نہیں۔
یوں لگتا ہے کہ معاشی حکمتِ عملی صرف خسارے کم کرنے اور IMF کی شرائط پوری کرنے تک محدود ہو گئی ہے، جبکہ طویل المیعاد سماجی و معاشی تحفظ کا کوئی واضح منصوبہ موجود نہیں۔ اس سے نہ صرف ریاست اور عوام کے درمیان فاصلہ بڑھے گا بلکہ بے روزگاری کا ایک نیا طوفان جنم لے گا، جس کے اثرات دیرپا اور مہلک ثابت ہو سکتے ہیں۔
یوٹیلٹی اسٹورز کی بندش کو اگر وسیع تر تناظر میں دیکھا جائے تو یہ حکومت کی اس پالیسی کا حصہ دکھائی دیتی ہے جس کے تحت خسارے میں جانے والے سرکاری اداروں کو یا تو بند کیا جا رہا ہے یا نجکاری کے حوالے کیا جا رہا ہے، جیسا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز -پی آئی اے کی نجکاری کی کوششیں اس وقت جاری ہیں۔ یہ پالیسیاں اصولاً غلط نہیں، مگر جس انداز میں انہیں نافذ کیا جا رہا ہے وہ مسائل کا ایک نیا باب کھول رہا ہے۔
سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ایسی پالیسیوں کے پیچھے کوئی واضح، متفقہ اور دیرپا فریم ورک موجود نہیں۔ یوٹیلٹی اسٹورز کو بند کرنے کا فیصلہ کئی بار بدلا گیا، اور حکومت کی جانب سے مسلسل متضاد بیانات سامنے آتے رہے۔ کبھی ان کی نجکاری کی بات ہوئی، کبھی اصلاحات کا اعلان ہوا، اور آخرکار بندش۔ اس غیر یقینی نے نہ صرف ادارے کے اندر کے افراد کو متاثر کیا، بلکہ عوام کو بھی کنفیوژن میں مبتلا رکھا۔
آج کا جدید ریٹیل سیکٹر مسابقتی، تیزرفتار، اور انتظامی چابک دستی کا متقاضی ہے، جبکہ یوٹیلٹی اسٹورز جیسے ادارے بدعنوانی، سیاسی مداخلت اور سست بیوروکریسی کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ لیکن اس حقیقت کے باوجود، ان کا وجود ایک ریاستی فلاحی وعدے کی نمائندگی کرتا تھا — ایک ایسا وعدہ جو اس بندش کے ساتھ ٹوٹ گیا۔